ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں:
’’میں متواتر ضرورت حدیث کے سلسلے میں آپ کے مضامین دیکھ چکا ہوں۔ میں نہ تو ان غالی مخالفین احادیث میں سے ہوں کہ کسی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دوں اور نہ کورا نہ روایات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے ان دو اصولی مسائل کے بارے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اور میرے احباب کی تسلی فرمائیں:
(۱) آیا قرآن مجید نجات کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اگر کافی ہے تو تفصیلات نماز وغیرہ جو غیر از قرآن ہیں، کیوں فریضہ اولین قرار دی جائیں؟
مزید قابل غور امر یہ ہے کہ باقی ارکان اسلام (روزہ، زکوٰۃ، حج جو سال میں یا عمر بھر میں ایک دفعہ ادا کرنے ضروری ہیں) کی تفصیلات تو قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن نماز جو ایک دن میں ۵ دفعہ ادا کرنی ضروری ہے اس کی تفصیلات کیوں بیان نہیں کرتا؟
(۲) الف۔ مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا روایات نہیں ہیں؟
ب۔ کوئی قوم جس کا شیرازہ منتشر ہوگیا ہو اور جس کے لیے مختلف آرڈر موجود ہوں اس وقت تک ترقی نہیں کرسکتی جب تک ایک آرڈر پر اصولی وحدت نہ ہو جائے۔ کیاروایات کو قبول کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے ایک آرڈر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ اس وقت مسلمان وحدت و یگانگت اور اتحاد ملی ہی سے نجات حاصل کرسکتے ہیں۔ اصولاً اس وحدت کا حل آپ کیا تجویز کریں گے؟‘‘
آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ اتنے پیچیدہ نہیں ہیں کہ تھوڑے سے تامل سے خود آپ ہی ان کا جواب نہ پا لیتے۔ میرے ان مضامین میں بھی جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان میں سے بعض سوالات کا حل موجود ہے۔ تاہم جب آپ کو ان مسائل میں الجھن پیش آرہی ہے اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس الجھن میں مبتلا ہیں تو ان کی تشفی کے لیے مختصراً کچھ عرض کیا جاتا ہے۔
(۱) قرآن حکیم’’نجات‘‘ کے لیے نہیں بلکہ ’’ہدایت‘‘ کے لیے کافی ہے۔ اس کا کام صحیح فکر اور صحیح عمل کی راہ بتانا ہے اور اس رہنمائی میں وہ یقیناً کافی ہے۔ مگر نجات کے لیے صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں اور وہی اعتقاد رکھیں جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے، اور اسی قانون کے مطابق عمل کریں جس کے اصول قرآن نے مقرر کیے ہیں۔
(۲) ہدایت کے لیے قرآن کے کافی ہونے کا مفہوم بھی عام طور پر غلط سمجھا جاتا ہے۔ کسی کتاب کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی علم یا فن کی تعلیم کے لیے کافی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس فن کے جتنے گُرہیں یا اس علم کے جتنے اہم مسائل ہیں، وہ سب اس کتاب میں آگئے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو اس کتاب کے الفاظ کو پڑھ سکتا ہو۔ اس کے تمام مطالب پر حاوی ہو جائے گا، اور محض کتاب کے مطالعے ہی سے اس کو اپنے فن میں اتنی مہارت بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہ عملاً اس سے کام لے سکے۔ کتاب اپنی جگہ کتنی ہی کامل سہی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری جانب خود طالب علم میں بھی ایک خاص استعداد موجود ہو اور ساتھ ہی ایک ماہر فن استاد بھی موجود ہو جو نہ صرف کتاب کے مطالب کی توضیح و تشریح کرے، بلکہ مظاہرہ (experiment)اور مشق و تمرین (exercise) کے ذریعے سے فن کی وہ عملی تفصیلات بھی سکھا دے جو نہ تو کتاب میں پوری طرح بیان ہوسکتی ہیں‘ اور نہ محض کتاب میں پڑھ لینے سے کوئی ان پر عمل و فضل کے اعتبار سے حاوی ہوسکتا ہے۔ پس یہی حال قرآن مجید کا بھی ہے۔ وہ اس لحاظ سے ہدایت کے لیے کافی ہے کہ اس میں وہ صحیح علم موجود ہے جس کی روشنی میں انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، اور اس میں وہ تمام اصول بیان کر دیئے گئے ہیں جس پر اللہ کا پسندیدہ دین قائم ہے۔ مگر اس علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ طالب علم استفادے کی خالص نیت رکھتا ہو اور ان مبادی سے واقف ہو جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک ماہر فن استاد موجود ہو جو کتاب اللہ کے نکات سمجھائے، آیات کا صحیح معنی و مفہوم بتائے، احکام پر خود عمل کرکے دکھائے اور قوانین کو عملی زندگی میں نافذ کرکے ان کا تفصیلی ضابطہ مقرر کر دے۔ پہلی چیز کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے ہے۔ رہی دوسری چیز تو اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غرض سے بھیجا گیا تھا کہ آپ اس ماہر فن کی ضرورت کو پورا کریں۔ آپ نے استاد کی حیثیت سے جو کچھ بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں ہے۔ جو شخص اس کی ضرورت کا منکر ہے اور قرآن کو اس معنی میں کافی سمجھتا ہے کہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و عملی ہدایت کی حاجت نہیں ہے وہ دراصل یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کی تنزیل کافی تھی، خدا نے نعوذ باللہ یہ فعل عبث کیا کہ اس کے ساتھ رسول کو بھی مبعوث کیا۔
(۳) آپ پوچھتے ہیں کہ ’’تفصیلات نماز وغیرہ جو غیر از قرآن ہیں کیوں فریضۂ اوّلین قرار دی جائیں؟‘‘ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفصیلات نمازوغیرہ کو غیر از قرآن کہنا ہی سرے سے غلط ہے۔ اگر کوئی ماہر فن طبیب فن طب کے کسی قاعدے کو عملی تجربہ کرکے شاگردوں کو سمجھائے تو آپ اسے ’’خارج از فن‘‘ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی پروفیسر اقلیدس کے کسی مسئلے کو شکلیں کھینچ کر تشریح و تفصیل کے ساتھ سمجھائے تو آپ اسے غیر از اقلیدس نہیں کہہ سکتے۔ ہر علم و فن کی اصولی کتابوں میں صرف اصول اور مہمات مسائل بیان کر دیئے جاتے ہیں اور عملی تفصیلات استاد کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں۔ کیونکہ استاد عملی مظاہرے سے جس بات کو چند لمحوں میں بتا سکتا ہے اسی کو اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو صفحے کے صفحے سیاہ ہو جائیں اور پھر بھی شاگردوں کے لیے لفظی بیان کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ پھر کتاب کے حسن کلام اور اس کے کمال ایجاز کا غارت ہو جانا مزید برآں۔ یہ حکیمانہ قاعدہ جس کو معمولی انسان تک اپنے علوم و فنون کی تعلیم میں ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ وہ سب سے بڑا حکیم جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نماز کے اوقات کا نقشہ بناتا، رکعتوں کی تفصیل دیتا، رکوع و سجود اور قیام و قعود کی صورتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ بلکہ نماز کی رائج الوقت کتابوں کی طرح ہر صورت کی تصویر بھی مقابل کے صفحات پر بنا دیتا۔ پھر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بھی لکھتا اور اس کے بعد وہ مختلف جزئی مسائل تحریر کرتا جن کے معلوم کرنے کی ہر نمازی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کے کم ازکم دو تین پارے صرف نماز کے لیے مخصوص ہو جاتے۔ پھر اسی طرح پر دو دو تین تین پارے روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل پر بھی مشتمل ہوتے۔ اس کے ساتھ شریعت کے دوسرے معاملات بھی جو قریب قریب زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، جزئیات کی پوری تفصیل کے ساتھ درج کتاب کیے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ آپ کی یہ خواہش تو پوری ہو جاتی کہ شریعت کا کوئی مسئلہ ’’غیر از قرآن نہ ہو‘‘ لیکن اس سے قرآن مجید کم از کم انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے برابر ضخیم ہو جاتا اور وہ تمام فوائد باطل ہو جاتے جو اس کتاب کو محض ایک مختصر سی اصولی کتاب رکھنے سے حاصل ہوئے ہیں۔
(۴) یہ تو آپ کو بھی تسلیم ہے کہ قرآن حکیم میں نماز، روزہ اور دوسرے ارکان اسلام کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں بلکہ صرف ان کی فرضیت پر زور دیا گیا ہے، ان کے قائم کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور کہیں کہیں ان کے ادا کرنے کے طریقوں کی طرف بھی اشارات کر دیئے گئے ہیں جو عملی تفصیلات پر کسی طرح بھی مشتمل نہیں کہے جاسکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی تفصیلات مقرر کرنے والا کون ہو؟ کیا یہ کام ہر شخص کے اختیار تمیزی پر چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ جو جس طرح چاہے عمل کرے؟ اگر ایسا ہوتا تو دو مسلمانوں کی نمازیں بھی شاید ایک طریقے پر نہ ہوتیں اور نہ دوسرے ارکانِ اسلام کے عملی طریقوں میں مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی ہم آہنگی پائی جاتی۔ آج آپ جس ’’شیرازۂ قومی‘‘ کے انتشار کا ماتم فرما رہے ہیں‘‘ وہ صرف چند آرڈروں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ تاہم ہر آرڈر میں لاکھوں کروڑوں مسلمان مجتمع ہیں۔ لیکن اگر ہرشخص قرآن کے احکام کی عملی تفصیلات مقرر کرنے میں خود مختار ہوتا تو اسلام کے پیرئووں میں سرے سے کوئی آرڈر ہی نہ ہوتا۔ ان مختلف افراد کو جس چیز نے ایک قوم بنایا ہے وہ اعتقاد و عمل کی یک رنگی و یکسانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ نظام جماعت کو قائم کرنے میں اعتقاد کے اشتراک سے بڑھ کر عمل کا اشتراک کارگر ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان حواس کا بندہ ہے اور اس کے حواس کو محسوس صورتیں ہی متاثر کرسکتی ہیں، اور انھی صورتوں کی یکسانی ویک رنگی اس میں جمعیت کا احساس پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا طریقہ ہائے عمل کو افراد کے اختیار پر چھوڑ دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ محض اعتقاد کے اشتراک سے مسلمان کبھی ایک قوم نہ بن سکتے۔
پس جب یہ مسلم ہے کہ وحدتِ قومی کے لیے اتحاد عمل ناگزیر ہے، اور یہ بھی مسلّم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ تفصیلات نہیں دی ہیں جن سے یہ اتحاد حاصل ہوسکتا تھا، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کو یہ حق پہنچتا تھا کہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کے طریقے اور ضابطے مقرر کرتا؟ اس کے سوا اورکس طریقے پر امت جمع ہوسکتی تھی؟ ان کے سوا اور کون تھا جسے حاکم اعلیٰ تسلیم کرکے سب مسلمان اس کی تقلید پر متفق ہو جاتے؟ یہ آںحضرت ہی کا فیض تعلیم تو ہے جس کی بدولت آج ساڑھے تیرہ سو برس سے تمام مسلمان ایک ہی ہیئت سے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے حج کرتے ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ فرق جو کچھ بھی ہے محض جزئیات کا ہے، اور وہ بھی اس بنا پر نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خود اپنے آپ کو ان جزئیات کے مقرر کرنے کا حق دار سمجھتا ہو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ ہر گروہ اپنے علم کے مطابق اسی جزئیہ کو آںحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون سمجھتا ہے جس پر وہ عامل ہے۔ باقی رہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، اور آپ کی سنت کا واجب التقلید ہونا، تو گنتی کے چند افراد کے سوا تمام امت اس پر متفق ہے، اور اسی اتفاق پر مسلمانوں کی وحدت قومی کا انحصار ہے۔
(۵)آپ قرآن مجید میں ایک مرتبہ پھر غور سے ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کے متعلق تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کن چیزوں پر کتنی زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ حج اور روزہ کے جن احکام کو آپ تفصیلات سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہ نماز کے احکام سے بھی زیادہ مجمل ہیں۔ آپ غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک اس قاعدے کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ پورا زور بیان ایمانیات کی تعلیم ہی میں صرف کر دیا جائے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے، رہے عبادات اور معاملات کے احکام، تو ان کے صرف اصول اور امہات مسائل بیان کر دیئے جائیں اور تفصیلات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا جائے۔
(۶) مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں ہیں بلکہ نفسانیت اور عصبیت ِ جاہلیہ، اور فروع کو اصول سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مزعومات میں حد سے زیادہ غلو کرنے کی عادت، اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو روایات کے اختلاف سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوسکتا۔ روایات خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور ان کے درمیان خواہ کتنا ہی اختلاف پایا جاتا ہو، بہرحال ان سب کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان مختلف روایتوں کو ماننے والے اس امر میں بہر طور متفق ہیں کہ وہ سب آںحضرت کو اپنا حاکم اور پیشوا مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں روایت کے اختلاف سے صرف فروع میں اختلاف واقع ہوتا ہے باقی رہے اصول دین تو وہ سب کے سب کتاب اللہ میں موجود ہیں جو روایات سے بالاتر اور تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ پس اگر مسلمان خلوص نیت کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کرلیں کہ وہ سب کتاب اللہ کے ماننے والے اور رسول اللہ کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان اصول دین مشترک ہیں، تو وہ جزئیات میں مختلف طریقوں پر قائم رہتے ہوئے بھی باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ادراک نہ ہو تو روایات کا سارا دفتر نذر آتش کر دینے سے بھی اختلاف دُور نہیں ہوسکتا۔ انسان کے نفس میں وہ شیطان موجود ہے جو قرآن کو بھی جنگ و جدل کا آلہ بنانے سے نہیں چوکتا۔
(۷) ’’ایک آرڈر‘‘ آپ کس معنی میں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ فروع میں کوئی اختلاف نہ ہو تو جب تک انسان کی فطرت نہ بدل جائے، یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔ بشری فطرت کے ساتھ تو یہ بھی ممکن نہیں کہ صرف دو ہی آدمیوں کا نقطۂ نظر بالکلیہ ایک ہو جائے۔ لہٰذا ایسا ’’ایک آرڈر‘‘ تو کبھی قائم نہیں ہوسکتا۔ جس میں کسی نوع کا اختلاف رائے اور اختلاف عمل سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ ہاں اگر آپ ’’ایک آرڈر‘‘ سے مراد ایسا آرڈر لیتے ہیں جو اصولوں کی وحدت پر مبنی ہو تو خدا کی کتاب اور اس کے رسول نے ایسا ہی آرڈر قائم کیا تھا اور ہر وقت ہوسکتا ہے بشرطیکہ مسلمان اصول اور فروع کا فرق سمجھ لیں اور دونوں کے مراتب میں امتیاز کرنا سیکھ جائیں۔
(ترجمان القرآن۔ شعبان ۱۳۵۳ھ۔ نومبر ۱۹۳۴ئ)
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
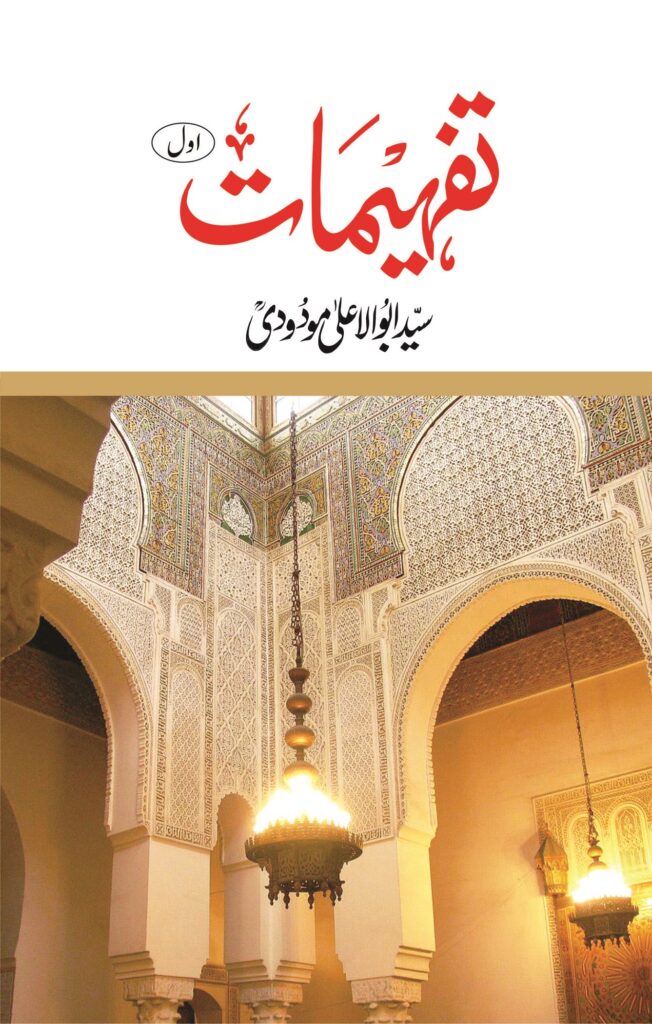

 by
by