تعبیر ِ دستور کا حق۲۱۷؎
سوال: دستور کی تعبیر کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ مقننہ کو یا عدلیہ کو؟ سابق دستور میں یہ حق عدلیہ کو تھا اور موجودہ دستور میں یہ حق عدلیہ سے چھین کر مقننہ کو ہی دے دیا گیا ہے۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ عدالتوں کے اختیارات کو کم کر دیا گیا ہے اور یہ حق عدلیہ کے پاس باقی رہنا چاہیے۔ اس مسئلے پر ایک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے دور اول میں عدالتوں کاکام صرف مقدمات کا فیصلہ کرنا تھا۔ قانون کی تشریح اور تعبیر کا حق عدالتوں کو نہ تھا اور نہ عدالتیں یہ طے کرنے کی مجاز تھیں کہ قانون صحیح ہے یا غلط۔ یہ رائے کہاں تک درست ہے؟۲۱۸؎
جواب: موجودہ زمانے کے قانونی و دستوری مسائل پر اسلام کے دور اول کی نظیریں چسپاں کرنے کا رجحان آج کل بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرح کے استدلال کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس عظیم الشان فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس وقت کے معاشرے اور ہمارے آج کے معاشرے میں‘ اور اس وقت کے کار فرمائوں اور اس دور کے کار فرمائوں میں فی الواقع موجود ہے۔
خلافت ِ راشدہ میں خلیفہ خود قرآن و سنت کا بہت بڑا عالم ہوتا تھا اور اس کی متقیانہ سیرت کی وجہ سے مسلمان اس پراعتماد رکھتے تھے کہ زندگی کے کسی مسئلے میں بھی اس کا اجتہاد کبھی دین کے راستے سے منحرف نہ ہوگا۔ اس کی مجلس شوریٰ کے ارکان بھی سب کے سب بلا استثنا اس بنیاد پر رکنیت کا شرف حاصل کرتے تھے کہ وہ قوم میں سب سے زیادہ دین کے جاننے اور سمجھنے والے ہیں۔ ان کے زمرے میں کوئی ایسا آدمی بار نہیں پاسکتا تھا جو دین سے جاہل ہو‘ یا نفسانیت کی بنا پر دین میں تحریف کرنے والا ہو‘ یا جس سے مسلمانوں کو کسی بدعت یا غیر اسلامی رجحان کا اندیشہ ہو۔ معاشرے کی عظیم اکثریت بھی اس وقت دین کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی اور کوئی شخص اس ماحول میں یہ جرأت نہ کرسکتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے خلاف کوئی حکم دے، یا کوئی قاعدہ و ضابطہ جاری کردے۔ یہی بلند معیار اس وقت کی عدالتوں کا بھی تھا۔ منصب قضا پر وہ لوگ سرفراز ہوتے تھے جو قرآن و سنت میں گہری بصیرت رکھتے تھے‘ کمال درجے کے متقی اور پرہیز گار تھے اور قانون خداوندی سے بال برابر بھی تجاوز کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان حالات میں مقننہ اور عدلیہ کے تعلقات کی وہی نوعیت تھی جو ایسے معاشرے میں ہونی چاہیے تھی۔ تمام جج مقدمات کے فیصلے براہ راست قرآن و سنت کے احکام کی بنیاد پر کرتے تھے اور جن امور میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی تھی ان میں بالعموم وہ خود اجتہاد کرتے تھے، البتہ جہاں معاملات کی نوعیت اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ جج اپنے انفرادی اجتہاد سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ خلیفہ کی مجلس شوریٰ ان میں شریعت کا حکم مشخص کرے‘ ان کے بارے میں اجتماعی اجتہاد سے ایک ایسا ضابطہ بنا دیا جاتا تھا جو دین کے اصولوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والا ہوسکتا تھا۔ اس نظام میں کوئی وجہ نہ تھی کہ ججوں کو مجلس شوریٰ کے بنائے ہوئے قانون پر نظرثانی کرنے کا اختیار ہوتا، کیونکہ وہ اگر کسی قانون کو رد کرنے کے مجاز ہو سکتے تھے تو اسی بنیاد پر تو ہوسکتے تھے کہ وہ اصل دستور (یعنی قرآن و سنت) کے خلاف ہے، اور قانون وہاں سرے سے کسی ایسے معاملے میں بنایا ہی نہیں جاتا تھا جس کے متعلق قرآن و سنت میں واضح حکم موجود ہو۔ قانون سازی کی ضرورت صرف ان معاملات میں پیش آتی تھی جن میں نص موجود نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد ناگزیر ہوتا تھا اور ایسے معاملات میں ظاہر ہے کہ انفرادی اجتہاد کی بہ نسبت اجتماعی اجتہاد زیادہ قابل اعتماد ہوسکتا تھا‘ خواہ بعض افراد کا ذاتی اجتہاد اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔
اب ظاہر ہے کہ اس وقت کی یہ دستوری نظیر آج کے حالات پر کسی طرح بھی چسپاں نہیں ہوتی، نہ آج کے حکمران اور مجالسِ قانون ساز کے ارکان خلفائے راشدین اور ان کی مجالسِ شوریٰ سے کوئی نسبت رکھتے ہیں‘ نہ آج کے جج اس وقت کے قاضیوں جیسے ہیں اور نہ اس دور کی قانون سازی ان حدود کی پابند ہے جن کی پابندی اس دور میں کی جاتی تھی۔ اس لیے اب آخر اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ ہم اپنے دستوری ضابطے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر تجویز کریں اور خلافت راشدہ کی نظیروں پر عمل شروع کرنے سے پہلے وہ حالات پیدا کرنے کی فکر کریں، جن سے وہ نظیریں عملاً تعلق رکھتی تھیں۔ موجودہ حالات میں جہاں تک شرعی معاملات کا تعلق ہے‘ آخری فیصلہ نہ انتظامیہ پر چھوڑا جاسکتا ہے‘ نہ مقننہ پر‘ نہ عدلیہ پر اور نہ مشاورتی کونسل پر۔ ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مسلمان شرعی امور میں اس پر کامل اعتماد کرسکیں۔ شریعت کو مسخ کرنے والے اجتہادات سے امن میسر آنے کی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رائے عام کو بیدار کیا جائے اور قوم بحیثیت مجموعی اس قسم کے ہر اجتہاد کی مزاحمت کے لیے تیار ہو۔ رہے عام دستوری مسائل‘ جن میں شریعت کوئی منفی یا مثبت احکام نہیں دیتی‘ ان میں مقننہ کو آخری فیصلہ کن اختیارات دے دینا بحالات موجودہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک غیر جانب دار ادارہ ایسا موجود ہونا چاہیے جو یہ دیکھ سکے کہ مقننہ نے کوئی قانون بنانے میں دستور کے حدود سے تجاوز تو نہیں کیا ہے اور ایسا ادارہ ظاہر ہے کہ عدلیہ ہی ہوسکتا ہے۔
اسلام اور جمہوریت۲۱۹؎
سوال: جمہوریت کو آج کل ایک بہترین نظام قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی نظام سیاست کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی حد تک جمہوری اصولوں پر مبنی ہے، مگر میری نگاہ میں جمہوریت کے بعض نقائص ایسے ہیں جن کے متعلق میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام انھیں کس طرح دور کرسکتا ہے۔ وہ نقائص درج ذیل ہیں:
۱۔ دوسرے سیاسی نظاموں کی طرح جمہوریت میں بھی عملاً آخر کار اقتدار جمہور کے ہاتھوں سے چھن کر اور چند افراد میں مرتکز ہو کر جنگ زرگری کی صورت اختیار کرلیتا ہے اور plutocracyیا oligarchyکی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا حل ممکن ہے؟
۲۔ عوام کے مُتَنَوّع اور متضاد مفادات کی بیک وقت رعایت ملحوظ رکھنا، نفسیاتی طور پر ایک بڑا مشکل کام ہے۔ جمہوریت اس عوامی ذمے داری سے کس شکل میں عہدہ برآ ہوسکتی ہے؟
۳۔ عوام کی اکثریت جاہل‘ سادہ لوح‘ بے حس اور شخصیت پرست ہے اور خود غرض عناصر انھیں برابر گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ان حالات میں نیابتی اور جمہوری ادارات کے لیے کامیابی سے کام کرنا بڑا دشوار ہے۔
۴۔ عوام کی تائید سے جو انتخابی اور نمائندہ مجالس وجود میں آتی ہیں‘ ان کے ارکان کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، اور ان کے مابین باہمی بحث و مشاورت اور آخری فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ کے خیال میں اسلام اپنے جمہوری ادارات میں ان خرابیوں کو راہ پانے سے کیسے روکے گا؟
جواب: آپ نے جمہوریت کے بارے میں جو تنقید کی ہے اس کے تمام نکات اپنی جگہ درست ہیں‘ لیکن اس مسئلے میں آخری رائے قائم کرنے سے پہلے چند اور نکات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔
اوّلین سوال یہ ہے کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے اصولاً کون سا طریقہ صحیح ہے؟
آیا یہ کہ وہ معاملات جن لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی مرضی سے سربراہ کار مقرر کیے جائیں اور وہ ان کے مشورے اوررضامندی سے معاملات چلائیں اور جب تک ان کا اعتماد سربراہ کاروں کو حاصل رہے اسی وقت تک وہ سربراہ کار رہیں؟ یا یہ کہ کوئی شخص یا گروہ خود سربراہِ کار بن بیٹھے اور اپنی مرضی سے معاملات چلائے اور اس کے تقرر اور علیحدگی اور کار پردازی میں سے کسی چیز میں بھی ان لوگوں کی مرضی و رائے کا کوئی دخل نہ ہو جن کے معاملات وہ چلا رہا ہو۔ اگر ان میں سے پہلی صورت ہی صحیح اور مبنی برانصاف ہے تو ہمارے لیے دوسری صورت کی طرف جانے کا راستہ پہلے ہی قدم پر بند ہو جانا چاہیے اور ساری بحث اس پر ہونی چاہیے کہ پہلی صورت کو عمل میں لانے کا زیادہ سے زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے۔
دوسری بات جو نگاہ میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اصول کو عمل میں لانے کی جو بے شمار شکلیں مختلف زمانوں میں اختیار کی گئی ہیں یا تجویز کی گئی ہیں‘ ان کی تفصیلات سے قطع نظر کرکے اگر انھیں صرف اس لحاظ سے جانچا اور پرکھا جائے کہ جمہوریت کے اصول اور مقصد کو پورا کرنے میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں‘ تو کوتاہی کے بنیادی اسباب صرف تین ہی پائے جاتے ہیں:
٭ اول یہ کہ ’’جمہور‘‘ کو مختار مطلق اور حاکم مطلق (sovereign)فرض کر لیا گیا اور اس بنا پر جمہوریت کو مطلق العنان بنانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ جب بجائے خود انسان ہی اس کائنات میں مختار مطلق نہیں ہے تو انسانوں پر مشتمل کوئی جمہور کیسے حاکمیت کا اہل ہوسکتا ہے۔ اسی بنا پر مطلق العنان جمہوریت قائم کرنے کی کوشش آخر کار جس چیز پر ختم ہوتی رہی ہے وہ جمہور پر چند آدمیوں کی عملی حاکمیت ہے۔ اسلام پہلے ہی قدم پر اس کا صحیح علاج کر دیتا ہے۔ وہ جمہوریت کو ایک ایسے بنیادی قانون کا پابند بناتا ہے جو کائنات کے اصل حاکم (sovereign)نے مقرر کیا ہے۔ اس قانون کی پابندی جمہور اور اس کے سربراہ کاروں کو لازماً کرنی پڑتی ہے۔ اس بنا پر وہ مطلق العنانی سرے سے پیدا ہی نہیں ہونے پاتی جو بالآخر جمہوریت کی ناکامی کا اصل سبب بنتی ہے۔
٭ دوم یہ کہ کوئی جمہوریت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک عوام میں اس کا بوجھ سہارنے کے لائق شعور اور مناسب اخلاق نہ ہوں۔ اسلام اسی لیے عام مسلمانوں کی فردًافردًا تعلیم اور اخلاقی تربیت پر زور دیتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد مسلمان میں ایمان اور احساس ذمہ داری اور اسلام کے بنیادی احکام کا اور ان کی پابندی کا ارادہ پیدا ہو۔ یہ چیز جتنی کم ہوگی جمہوریت کی کامیابی کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے اور یہ جتنی زیادہ ہوگی‘ امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔
٭ سوم یہ کہ جمہوریت کے کامیابی کے ساتھ چلنے کا انحصار ایک بیدار مضبوط رائے عام پر ہے اور اس طرح کی رائے عامہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرہ اچھے افراد پر مشتمل ہو۔ ان افراد کو صالح بنیادوں پر ایک اجتماعی نظام میں منسلک کیا گیا ہو، اور اس اجتماعی نظام میں اتنی طاقت موجود ہو کہ برائی اور برے اس میں نہ پھل پھول سکیں اور نیکی اور نیک لوگ ہی اس میں ابھر سکیں۔ اسلام نے اس کے لیے بھی ہم کو تمام ضروری ہدایات دے دی ہیں۔
اگر مندرجہ بالا تینوں اسباب فراہم ہو جائیں تو جمہوریت پر عمل درآمد کی مشینری خواہ کسی طرح کی بنائی جائے‘ وہ کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے اور اس مشینری میں کسی جگہ کوئی قباحت محسوس ہو تو اس کی اصلاح کرکے بہتر مشینری بھی بنائی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد اصلاح و ارتقا کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جمہوریت کو تجربے کا موقع ملے۔ تجربات سے بتدریج ایک ناقص مشینری بہتر اور کامل تر بنتی چلی جائے گی۔
صدر ریاست کو ویٹو کا حق۲۲۰؎
سوال: کچھ عرصے سے اخبارات کے ذریعے سے تجاویز پیش کی جارہی ہیں کہ صدر پاکستان کو خلیفۃ المسلمین یا امیرالمومنین کے معزز خطاب سے آراستہ کیا جائے۔ اس تصور میں مزید جان ڈالنے کے لیے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ صدر کو حقِ تنسیخ ملنا چاہیے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے جلیل القدر صحابہ کے مقابلے میں ویٹو سے کام لیا،اور منکرین زکوٰۃ و مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے جہاد کا حکم دے کر صحابہؓکی رائے کو رد کر دیا۔ گویا اس دلیل سے شرعی حیثیت کے ساتھ ویٹو جیسے دھاندلی آمیز قانون کو مستحکم فرمایا جارہا ہے۔
ان حالات کی روشنی میں جناب والا کی خدمت میں چند سوالات پیش کیے جارہے ہیں۔ امید ہے کہ بصراحت جوابات سے مطمئن فرمائیں گے۔
۱۔ کیا حضرت ابوبکرؓ نے آج کے معنوں میں ویٹو استعمال فرمایا تھا؟
۲۔ اگر استعمال فرمایا تھا تو ان کے پاس کوئی شرعی دلیل تھی یا نہیں؟
جواب: خلفائے راشدین کی حکومت کے نظام اور آج کل کے صدارتی نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان دونوں کو ایک چیز صرف وہی لوگ قرار دے سکتے ہیں جو اسلام کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ میں نے اس فرق پر مفصل بحث باب ۷ کا ذیلی عنوان: مختلف اعضائے ریاست کا باہمی تعلق میں کی ہے، ملاحظہ فرمالیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس چیز کو خلافت کے نظام میں ’ویٹو‘ کے اختیارات سے تعبیر کیا جارہا ہے وہ موجودہ زمانے کی دستوری اصطلاح سے بالکل مختلف چیز تھی۔ حضرت ابوبکرؓ کے صرف دو فیصلے ہیں جن کو اس معاملے میں بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ ایک: جیشِ اسامہؓ کا معاملہ۔ دوسرے: مرتدین کے خلاف جہاد کا مسئلہ۔ ان دونوں معاملات میں حضرت ابوبکرؓ نے محض اپنی ذاتی رائے پر فیصلہ نہیں کردیا تھا‘ بلکہ اپنی رائے کے حق میں کتاب و سنت سے استدلال کیا تھا۔ جیشِ اسامہؓ کے معاملے میں ان کا استدلال یہ تھا کہ جس کام کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں کرچکے تھے، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انجام دینا میرا فرض ہے۔ میں اسے بدل دینے کے اختیارات نہیں رکھتا۔ مرتدین کے معاملے میں ان کا استدلال یہ تھا کہ جو شخص یا گروہ بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہو‘ اور یہ کہے کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا وہ مرتد ہے‘ اسے مسلمان سمجھنا ہی غلط ہے‘ لہٰذا ان لوگوں کی دلیل قابل قبول نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے قائلین پر تم کیسے تلوار اٹھائو گے۔ یہی دلائل تھے جن کی بنا پر صحابہ کرامؓ نے حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ یہ اگر ’ویٹو‘ ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹو ہے نہ کہ سربراہِ ریاست کا۔
حقیقت میں اسے ویٹو کہنا ہی سرے سے غلط ہے‘ کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے استدلال کو تسلیم کرلینے کے بعد اختلاف کرنے والے صحابہ کرامؓ اس کی صحت کے قائل ہوگئے تھے اور اپنی سابقہ رائے سے انھوں نے رجوع کرلیا تھا۔
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
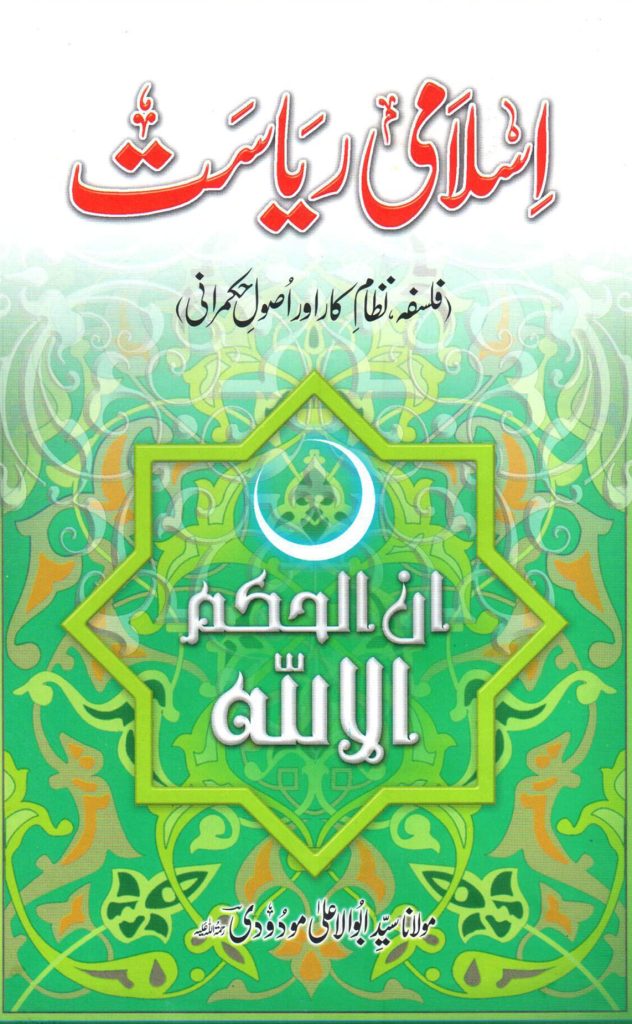

 by
by