تیسرا مابعدالطبیعی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دُنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے ایک دارالعذاب ہے۔ انسان کی روح اس قفسِ عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لذات و خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں دراصل اس قید خانہ کے طوق و سلاسل ہیں۔ انسان اس دُنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہو گا اور اِسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ نجات کی صورت اس کے سِوا کوئی نہیں کہ اس زِندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے ، خواہشات کو مٹایا جائے ، لذات سے کنارہ کشی کی جائے ، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے ، ان تمام محبتوں کو جو دنیوی اشیا اور گوشت و خون کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، دل سے نکال دیا جائے اور اپنے اس دشمن ، یعنی نفس و جسم کو مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی۔
یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی (anti-social)نظریہ ہے ، مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر اندازہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانتزام ، مانویت ، اشراقیت (neo-platonism) یوگ ، تصوف ، مسیحی رہبانیت اور بدھ ازم وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ اس فلسفہ کے ساتھ ایک ایسا نظامِ اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی (positive) اور بہت زیادہ ، بلکہ تمام تر سلبی (negative) نوعیت کا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جل کر لٹریچر ، عقائد ، اخلاقیات اور عملی زِندگی میں نفوذ کرتی ہیں اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں۔
پہلی دونوں قسم کی جاہلیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیّت کا تعاون عموماً تین صورتوں سے ہوتا ہے۔
(۱) راہبانہ جاہلیّت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دُنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشہ ِ عزلت میں لے جاتی ہے اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے۔ بدکار لوگ خدا کی زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپسیا کیے چلے جاتے ہیں۔
(۲) اس جاہلیّت کے اثرات جہاں تک عوام میں پہنچتے ہیں وہ ان کے اندر غلط قسم کا صبر و تحمل اور مایوسانہ نقطہ نظر پیدا کرکے انھیں ظالموں کے لیے نرم نوالہ بنا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ بادشاہ ، امرا اور مذہبی اقتدار رکھنے والے طبقے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی اشاعت میں خاص دل چسپی لیتے رہے ہیں اور یہ خوب آرام سے ان کی سرپرستی میں پھیلتا رہا ہے۔ تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ امپیریلزم ، سرمایہ داری اور پاپائیت سے اس راہبانہ فلسفہ و اخلاق کی کبھی لڑائی ہوئی ہو۔
(۳) جب یہ راہبانہ فلسفہ و اخلاق انسانی فطرت سے شکست کھا جاتا ہے تو کتاب الحیل کی تصنیف شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کفارے کا عقیدہ ایجاد ہوتا ہے تاکہ دل کھول کر گناہ کیا جا سکے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ کہیں ہوس رانی کے لیے عشق مجازی کا حیلہ نکالا جاتا ہے تاکہ دل کی لگی بجھا بھی لی جائے اور تقدس بھی جوں کا توں قائم رہے۔ اور کہیں ترک دُنیا کے پردے میں بادشاہوں اور رئیسوں سے سانٹھ گانٹھ کی جاتی ہے اور روحانی امارت کا وہ جال پھیلایا جاتا ہے جس کی بدترین مثالیں روم کے پاپائوں اور مشرقی دُنیا کے گدی نشینوں نے پیش کی ہیں۔
یہ تو اس جاہلیّت کا معاملہ اپنی ہم جنس بہنوں کے ساتھ ہے۔ مگر انبیا علیہم السلام کی امتوں میں جب یہ گھس آتی ہے تو کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے۔ خدا کے دین پر اس کی پہلی ضرب یہ ہوتی ہے کہ یہ دُنیا کو دارالعمل ، دارالامتحان اور مزرعۃ الآخرۃ کی بجائے دارالعذاب اور ’’مایا کے جال‘‘ کی حیثیت سے آدمی کے سامنے پیش کرتی ہے نقطہ نظر کے اس بنیادی تغیر کی وجہ سے آدمی یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ وہ اس دُنیا میں خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہے۔ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ میں یہاں کام کرنے اور دُنیا کے معاملات کو چلانے نہیں آیا ہوں بلکہ گندگی و نجاست میں پھینکا گیا ہوں جس سے مجھے بچنا اور دور بھاگنا چاہیے۔ میرے لیے صحیح پوزیشن یہ ہے کہ میں یہاں نان کوآپریٹر کی طرح رہوں اور ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی بجائے ان سے کنارہ کروں۔ اس تصور کے ساتھ آدمی دُنیا اور اس کے معاملات پر سہمی ہوئی نگاہ ڈالنے لگتا ہے اور بارِ خلافت کو سنبھالنا تو درکنار ، بارِ تمدن کو بھی اپنے سر لیتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے پورا نظامِ شریعت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عبادات اور اوامر و نواہی کا یہ مفہوم بالکل ساقط ہو جاتا ہے کہ یہ حیاتِ دُنیا کی اصلاح اور فرائض خلافت کی انجام دہی کے لیے تیار کرنے والی چیزیں ہیں ، برعکس اس کے آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عبادات اور چند خاص مذہبی اعمال اس گناہِ زِندگی کا کفارہ ہیں بس انھی کو پورے انہماک سے ٹھیک ناپ تول کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔
اس ذہنیت نے انبیا کی امتوں میں سے ایک گروہ کو مراقبہ و مکاشفہ ، چلہ کشی و ریاضت، اورا وراد وظائف، احزاب و اعمال،({ FR 6683 }) سیر مقامات ({ FR 6684 }) اور حقیقت کی فلسفیانہ تعبیروں ({ FR 6685 }) کے چکر میں ڈال دیا اور مستحبات و نوافل کے التزام میں فرائض سے بھی زیادہ منہمک کرکے خلافتِ الٰہیہ کے اس کام سے غافل کر دیا جسے جاری کرنے کے لیے انبیا علیہم السلام آئے تھے۔ اور دوسرے گروہ میں تقشف ، تعمق فی الدین ، غلو ، موشگافی ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ناپ تول اور جزئیات کے ساتھ غیر معمولی اہتمام کی بیماری پیدا کر دی ، حتّٰی کہ ان کے لیے خدا کا دین ایک ایسا نازک آبگینہ ہو گیا جو ذرا ذرا سی باتوں سے ٹھیس کھا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بے چاروں کا سارا وقت بس اسی دیکھ بھال کی نذر ہونے لگا کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے اور یہ شیشے کا برتن جو سر پر رکھا ہے۔ کھیل کھیل ہو کر نہ رہ جائے۔ دین میں اتنی باریکیاں نکل آنے کے بعد ناگزیر ہے کہ جمود ، تنگ خیالی اور کم حوصلگی پیدا ہو۔ ایسے لوگوں میں کہاں یہ قابلیت باقی رہ سکتی ہے کہ نگاہِ جہاں بیں سے انسانی زِندگی کے بڑے بڑے مسائل پر نظر ڈالیں ، دین کے عالم گیر اصول و کلیات پر گرفت حاصل کریں اور زمانہ کی ہر نئی گردش میں دُنیا کی امامت و راہ نُمائی کے لیے مستعد ہوں۔
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
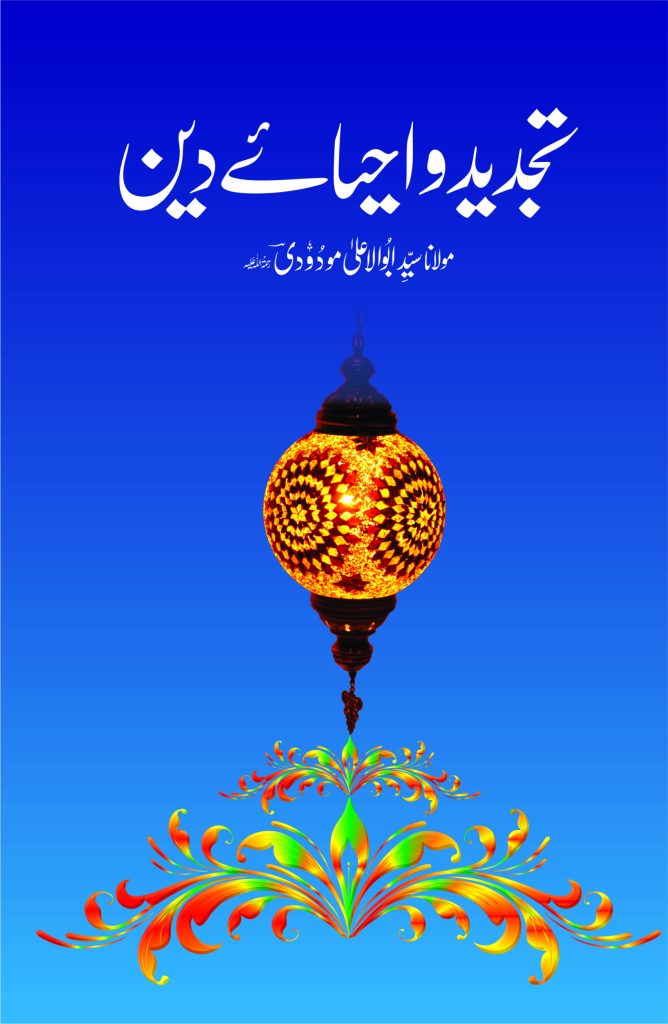

 by
by