زمانۂ حال میں مسلمانوں کی جماعت کے لیے لفظ ’قوم‘ کا استعمال کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور عموماً یہی اصطلاح ہماری اجتماعی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے رائج ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور بعض حلقوں کی طرف سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کے لیے لفظ ’قوم‘ (یانیشن کے معنی میں کسی دوسرے لفظ کو) اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ میں اصلی قباحت کیا ہے جس کی وجہ سے اسلام میں ان سے پرہیز کیا گیا اور وہ دوسرے الفاظ کون سے ہیں جن کو قرآن و حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک علمی بحث نہیں ہے‘ بلکہ اس سے ہمارے ان بہت سے تصورات کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جن کی بدولت زندگی میں ہمارا رویہ بنیادی طور پر غلط ہو کر رہ گیا ہے۔
لفظ ’قوم‘ اور اس کے ہم معنی انگریزی لفظ nation‘ دونوں دراصل جاہلیت کی اصطلاحیں ہیں۔ اہل جاہلیت نے ’’قومیت‘‘ (nationality)کو کبھی خالص تہذیبی بنیاد (cultural basis)پر قائم نہیں کیا‘ نہ قدیم جاہلیت کے دور میں اور نہ جدید جاہلیت کے دور میں۔ ان کے دل و دماغ کے ریشوں میں نسلی اور روایتی علائق کی محبت کچھ اس طرح پلا دی گئی ہے کہ وہ نسلی روابط اور تاریخی روایات کی وابستگی سے قومیت کے تصور کو کبھی پاک نہ کرسکے۔ جس طرح قدیم عرب میں قوم کا لفظ عموماً ایک نسل یا ایک قبیلے کے لوگوں پر بولا جاتا تھا اسی طرح آج بھی لفظ ’نیشن‘ کے مفہوم میں مشترک جنسیت (common descent) کا تصور لازمی طور پر شامل ہے اور یہ چیز چونکہ بنیادی طور پر اسلامی تصورِ اجتماع کے خلاف ہے، اس وجہ سے قرآن میں لفظ قوم اور اس کے ہم معنی دوسرے عربی الفاظ مثلاً شُعَب وغیرہ کو مسلمانوں کی جماعت کے لیے اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی اصطلاح اس جماعت کے لیے کیوں کر استعمال کی جاسکتی تھی جس کے اجتماع کی اساس میں خون اور خاک اور رنگ اور اس نوع کی دوسری چیزوں کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا‘ جس کی تالیف و ترکیب محض اصول اور مسلک کی بنیاد پر کی گئی تھی اور جس کا آغاز ہی ہجرت اور قطعِ نسب اور ترکِ علائق مادی سے ہوا تھا۔
قرآن نے جو لفظ مسلمانوں کی جماعت کے لیے استعمال کیا ہے وہ’حزب‘ ہے، جس کے معنی پارٹی کے ہیں۔ قومیں نسل و نسب کی بنیاد پر اٹھتی ہیں اور پارٹیاں اصول و مسلک کی بنیاد پر۔ اس لحاظ سے مسلمان حقیقت میں قوم نہیں بلکہ ایک پارٹی ہیں، کیونکہ ان کو تمام دنیا سے الگ اور ایک دوسرے سے وابستہ صرف اس بنا پر کیا گیا ہے کہ یہ ایک اصول اور مسلک کے معتقد اور پیرو ہیں اور جن سے ان کا اصول و مسلک میں اشتراک نہیں، وہ خواہ ان سے قریب ترین مادی رشتے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں‘ ان کے ساتھ ان کا کوئی میل نہیں ہے۔ قرآن رُوئے زمین کی اس پوری آبادی میں صرف دو ہی پارٹیاں دیکھتا ہے۔ ایک اللہ کی پارٹی (حِزبُ اللہ)، دوسرے شیطان کی پارٹی (حِزبُ الشیطان) شیطان کی پارٹی میں خواہ باہم اصول و مسلک کے اعتبار سے کتنے ہی اختلافات ہوں‘ قرآن ان سب کو ایک سمجھتا ہے، کیونکہ ان کا طریقِ فکر اور طریقِ عمل بہرحال اسلام نہیں ہے اور جزئی اختلافات کے باوجود بہرحال وہ سب شیطان کے اتباع پر متفق ہیں۔ قرآن کہتا ہے:
اِسْتَحْوَذَ عَلَيْہِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰـىہُمْ ذِكْرَ اللہِ۰ۭ اُولٰۗىِٕكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ۰ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ ہُمُ الْخٰسِرُوْنَ المجادلۃ 19:58
شیطان ان پر غالب آگیا اور اس نے خدا سے انھیں غافل کر دیا۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور جان رکھو کہ شیطان کی پارٹی آخر کار نامراد ہی رہنے والی ہے۔
برعکس اس کے اللہ کی پارٹی والے خواہ نسل اور وطن اور زبان اور تاریخی روایات کے اعتبار سے باہم کتنے ہی مختلف ہوں‘ بلکہ چاہے ان کے آبائواجداد میںباہم خونی عداوتیں ہی کیوں نہ رہ چکی ہوں، جب وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقِ فکر اور مسلکِ حیات میں متفق ہوگئے تو گویا الٰہی رشتے (حَبلُ اللہ) سے باہم جڑ گئے اور اس نئی پارٹی میں داخل ہوتے ہی ان کے تمام تعلقات حِزبُ الشیطان والوں سے کٹ گئے۔
پارٹی کا یہ اختلاف باپ اور بیٹے تک کا تعلق توڑ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بیٹا باپ کی وراثت تک نہیں پاسکتا۔ حدیث کے الفاظ میں: لَایَتَوَارَثُ اَھْلُ مِلَّتَیْنِ۔ (ترمذی ۲۱۰۸۔ مشکوۃ ۲۹۱۵ ابودائود، ابن ماجہ) دو مختلف ملتوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوسکتے‘۔
پارٹی کا یہ اختلاف بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے حتیٰ کہ اختلاف رونما ہوتے ہی دونوں پر ایک دوسرے کی مواصلت حرام ہو جاتی ہے‘ محض اس لیے کہ دونوں کی زندگی کے راستے جدا ہوچکے۔ قرآن میں ہے: لَا ہُنَّ حِلٌّ لَّہُمْ وَلَا ہُمْ يَحِلُّوْنَ لَہُنَّ۰ۭ الممتحنۃ 10:60
نہ وہ ان کے لیے حلال‘ نہ یہ ان کے لیے حلال۔
پارٹی کا یہ اختلاف ایک برادری‘ ایک خاندان کے آدمیوں میں پورا معاشرتی مقاطعہ کرا دیتا ہے‘ حتیٰ کہ حزب اللہ والے کے لیے خود اپنی نسلی برادری کے ان لوگوں میں شادی بیاہ کرنا حرام ہو جاتا ہے جو حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے :
مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن لونڈی‘ مشرک بیگم سے بہتر ہے‘ خواہ وہ تمھیں کتنی ہی پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن غلام مشرک آزاد شخص سے بہتر ہے‘ چاہے وہ تمھیں کتنا ہی پسند ہو۔ (البقرہ۲:۲۲۱)
پارٹی کا یہ اختلاف نسلی و وطنی قومیت کا تعلق صرف کاٹ ہی نہیں دیتا، بلکہ دونوں میں ایک مستقل نزاع قائم کر دیتا ہے جو دائمًا قائم رہتی ہے تاوقتیکہ وہ اللہ کی پارٹی کے اصول تسلیم نہ کرلیں۔ قرآن کہتا ہے:
۱۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَۃٌ حَسَـنَۃٌ فِيْٓ اِبْرٰہِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَہٗ۰ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِہِمْ اِنَّا بُرَءٰۗؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ۰ۡكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَۃُ وَالْبَغْضَاۗءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللہِ وَحْدَہٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰہِيْمَ لِاَبِيْہِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ الممتحنہ 4:60
تمھارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم ؑ اور اس کے ساتھیوں میں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی (نسلی) قوم والوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا تم سے اور تمھارے ان مبعودوں سے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو‘ کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تم سے بے تعلق ہو چکے اور ہمارے تمھارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی تاوقتیکہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لائو، مگر تمھارے لیے ابراہیمؑ کے اس قول میں نمونہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے (کافر) باپ سے کہا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروںگا:
۲۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰہِيْمَ لِاَبِيْہِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَۃٍ وَّعَدَھَآ اِيَّاہُ۰ۚ فَلَمَّا تَـبَيَّنَ لَہٗٓ اَنَّہٗ عَدُوٌّ لِّلہِ تَبَرَّاَ مِنْہُ۰ۭ التوبہ114:9
ابراہیم ؑ کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا محض اس وعدے کی بنا پر تھا جووہ اس سے کرچکا تھا، مگر جب اس پر کھل گیا کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہوگیا۔
پارٹی کا یہ اختلاف ایک خاندان والوں اور قریب ترین رشتہ داروں کے درمیان بھی محبت کا تعلق حرام کر دیتا ہے‘ حتیٰ کہ اگر باپ اور بھائی اور بیٹے بھی حزب الشیطان میں شامل ہوں تو حزب اللہ والا اپنی پارٹی سے غداری کرے گا اگر ان سے محبت رکھے۔ قرآن میں ارشاد ہے:
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللہِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَاۗدُّوْنَ مَنْ حَاۗدَّ اللہَ وَرَسُوْلَہٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَاۗءَہُمْ اَوْ اَبْنَاۗءَہُمْ اَوْ اِخْوَانَہُمْ اَوْ عَشِيْرَتَہُمْ۰ۭ …… اُولٰۗىِٕكَ حِزْبُ اللہِ۰ۭ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللہِ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَo
المجادلۃ 22:58
تم ایسا ہرگز نہ پائو گے کہ کوئی جماعت اللہ اور یوم آخر پر ایمان بھی رکھتی ہو، اور پھر اللہ اور رسولؐ کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے‘ خواہ وہ ان کے باپ‘ بیٹے‘ بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں…… یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور جان رکھو کہ آخر کار اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔
دوسرا لفظ پارٹی ہی کے معنی میں قرآن نے مسلمانوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ لفظ ’امت‘ ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ کثرت سے مستعمل ہوا ہے۔ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو کسی امر جامع نے مجتمع کیا ہو۔ جن افراد کے درمیان کوئی اصل مشترک ہو، ان کو اسی اصل کے لحاظ سے’امت‘ کہا جاتا ہے۔ مثلاً: ایک زمانے کے لوگ بھی ’امت‘ کہے جاتے ہیں۔ ایک نسل یا ایک ملک کے لوگ بھی ’امت‘ کہے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو جس اصل مشترک کی بنا پر امت کہا گیا ہے وہ نسل یا وطن یا معاشی اغراض نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی زندگی کا مشن اور ان کی پارٹی کا اصول اور مسلک ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے:
۱۔ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللہِ۰ۭ
آل عمران 110:3
تم وہ بہترین امت ہو جسے نوعِ انسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔
۲۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّۃً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُہَدَاۗءَ عَلَي النَّاسِ وَيَكُـوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَہِيْدًا۰ۭ البقرہ143:2
اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا ہے تاکہ تم نوع انسانی پر نگران ہو اور رسولؐ تم پر نگران ہو۔
ان آیات پر غور کیجیے۔ ’بیچ کی امت‘ سے مراد یہ ہے کہ’مسلمان‘ ایک بین الاقوامی جماعت (international party) کا نام ہے۔ دنیا کی ساری قوموں میں سے ان اشخاص کو چھانٹ کر نکالا گیا ہے جو ایک خاص اصول کو ماننے‘ ایک خاص پروگرام کو عمل میں لانے اور ایک خاص مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ چونکہ ہر قوم میں سے نکلے ہیں اور ایک پارٹی بن جانے کے بعد کسی قوم سے ان کا تعلق نہیں رہا ہے، اس لیے یہ بیچ کی امت ہیں۔ لیکن ہر ہر قوم سے تعلق توڑنے کے بعد سب قوموں سے ان کا ایک دوسرا تعلق قائم کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں خدائی قانون کو قائم کرنے کے فرائض انجام دیں۔ ’تم نوع انسانی پر نگران ہو‘ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ مسلمان خدا کی طرف سے دنیا میں فوج دار مقرر کیا گیا ہے اور ’نوع انسانی کے لیے نکالا گیا ہے‘ کا فقرہ صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا مشن ایک عالم گیر مشن ہے۔ اس مشن کا خلاصہ یہ ہے کہ ’حزب اللہ‘ کے لیڈر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر و عمل کا جو ضابطہ خدا نے دیا تھا اس کو تمام ذہنی‘ اخلاقی اور مادی طاقتوں سے کام لے کر دنیا میں نافذ کیا جائے اور اس کے مقابلے میں ہر دوسرے طریقے کو مغلوب کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر مسلمان ایک امت بنائے گئے ہیں۔
تیسرا اصطلاحی لفظ جو مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت استعمال کیا ہے وہ لفظ ’جماعت‘ ہے اور یہ لفظ بھی ’حزب‘ کی طرح بالکل پارٹی کا ہم معنی ہے۔ عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَۃِ اور یَدُ اللّٰہِ عَلَی الْجَمَاعَۃِ (ترمذی‘ ۲۱۶۷) اور ایسی ہی بکثرت احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ’قوم‘ یا ’شعب‘ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ استعمال کرنے سے قصداً احتراز فرمایا اور ان کے بجائے ’جماعت‘ ہی کی اصطلاح استعمال کی۔ آپؐ نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ’ہمیشہ قوم کے ساتھ رہو‘ یا ’قوم پر خدا کا ہاتھ ہے‘ بلکہ ایسے تمام مواقع پر آپؐ جماعت ہی کا لفظ استعمال فرماتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے اور یہی ہوسکتی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع کی نوعیت ظاہر کرنے کے لیے’قوم‘ کے بجائے جماعت‘ حزب اور پارٹی کے الفاظ ہی زیادہ مناسب ہیں۔ ’قوم‘ کا لفظ جن معنوں میں عموماً مستعمل ہوتا ہے، ان کے لحاظ سے ایک شخص خواہ وہ کسی مسلک اور کسی اصول کا پیرو ہو‘ ایک قوم میں شامل رہ سکتا ہے جب کہ وہ اس قوم میں پیدا ہوا ہو اور اپنے نام‘ طرز زندگی اور معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے اس قوم کے ساتھ منسلک ہو، لیکن پارٹی‘ جماعت اور حزب کے الفاظ جن معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے اصول اور مسلک ہی پر پارٹی میں شامل ہونے‘ یا اس سے خارج ہونے کا مدار ہوتا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے اصول و مسلک سے ہٹ جانے کے بعد ہرگز اس میں شامل نہیں رہ سکتے‘ نہ اس کا نام استعمال کرسکتے ہیں، نہ اُس کے نمایندے بن سکتے ہیں، نہ اُس کے مفاد کے محافظ بن کر نمودار ہوسکتے ہیںاور نہ پارٹی والوں سے آپ کا کسی طور پر تعاون ہوسکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پارٹی کے اصول و مسلک سے تو متفق نہیں ہوں‘ لیکن میرے والدین اس پارٹی کے ممبر رہ چکے ہیں‘ اور میرا نام اس کے ممبروں سے ملتا جلتا ہے اس لیے مجھ کو بھی ممبروں کے سے حقوق ملنے چاہییں تو آپ کا یہ استدلال اتنا مضحکہ انگیز ہوگا کہ شاید سننے والوں کو آپ کی دماغی حالت پر شبہہ ہونے لگے گا، لیکن پارٹی کے تصور کو قوم کے تصور سے بدل ڈالیے، اس کے بعد یہ سب حرکات کرنے کی گنجایش نکل آتی ہے۔
اسلام نے اپنی بین الاقوامی پارٹی کے ارکان میں یک جہتی اور ان کی معاشرت میں یکسانی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو ایک سوسائٹی بنا دینے کے لیے حکم دیا تھا کہ آپس ہی میں بیاہ شادی کرو۔ اس کے ساتھ ہی ان کی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام تجویز کیا گیا تھا کہ وہ خودبخود پارٹی کے اصول و مسلک کے پیرو بن کر اٹھیں اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ افزائش نسل سے بھی پارٹی کی قوت بڑھتی رہے۔ یہیں سے اس پارٹی کے قوم بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ بعد میں مشترک معاشرت‘ نسلی تعلقات اور تاریخی روایات نے اس قومیت کو زیادہ مستحکم کر دیا۔
اس حد تک جو کچھ ہوا‘ درست ہوا، لیکن رفتہ رفتہ مسلمان اس حقیقت کو بھولتے چلے گئے کہ وہ دراصل ایک پارٹی ہیں‘ اور پارٹی ہونے کی حیثیت ہی پر ان کی قومیت کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ بھُلاوا بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پارٹی کا تصور قومیت کے تصور میں بالکل ہی گم ہوگیا۔ مسلمان اب صرف ایک قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح کی ایک قوم جیسی کہ جرمن ایک قوم ہے یا جاپانی ایک قوم ہے یا انگریز ایک قوم ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ اصل چیز وہ اصول اور مسلک ہیں جس پر اسلام نے ان کو ایک امت بنایا تھا‘ وہ مشن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے پیروئوں کو ایک پارٹی کی صورت میں منظم کیا تھا۔ اس حقیقت کو فراموش کرکے انھوں نے غیر مسلم قوموں سے ’قومیت‘ کا جاہلی تصور لے لیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی غلطی ہے اور اس کے قبیح اثرات اتنے پھیل گئے ہیں کہ احیائے اسلام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ اس غلطی کو دور نہ کر دیا جائے۔
ایک پارٹی کے ارکان میں باہمی محبت‘ رفاقت اور معاونت جو کچھ بھی ہوتی ہے شخصی یا خاندانی حیثیت سے نہیں ہوتی‘ بلکہ صرف اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ سب ایک اصول کے معتقد اور ایک مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔ پارٹی کا ایک رکن اگر جماعتی اصول اور مسلک سے ہٹ کر کوئی کام کرے تو صرف یہی نہیں کہ اس کی مدد کرنا پارٹی والوں کا فرض نہیں ہوتا‘ بلکہ اس کے برعکس پارٹی والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے غدارانہ اور باغیانہ طرز عمل سے روکیں‘ نہ مانے تو اس کے خلاف جماعتی ضوابط کے تحت سخت کارروائی کریں‘ پھر بھی نہ مانے تو جماعت سے نکال باہر کریں۔ ایسی مثالیں بھی دنیا میں ناپید نہیں ہیں کہ جو شخص پارٹی کے مسلک سے شدید انحراف کرتا ہے اسے کچھ خاص حالتوں میں قتل تک کر دیا جاتا ہے۔۷۷؎ لیکن ذرا مسلمانوں کا حال دیکھیے کہ اپنے آپ کو پارٹی کے بجائے قوم سمجھنے کی وجہ سے یہ کیسی شدید غلط فہمی میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ ان میں سے جب کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے غیر اسلامی اصولوں پر کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں سے توقع رکھتا ہے کہ اس کی مدد کریں گے۔ اگر مدد نہیں کی جاتی تو شکایت کرتا ہے کہ دیکھو‘ مسلمان مسلمان کے کام نہیں آتے۔ سفارش کرنے والے ان کی سفارش ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کا بھلا ہوتا ہے‘ اس کی مدد کرو۔ مدد کرنے والے بھی اگر اس کی مدد کرتے ہیں تو اپنے اس فعل کو اسلامی ہمدردی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں ہر ایک کی زبان پر اسلامی ہمدردی‘ اسلامی برادری‘ اسلام کے رشتۂ دینی کا نام بار بار آتا ہے۔ حالانکہ درحقیقت اسلام کے خلاف عمل کرنے میں خود اسلام ہی کا حوالہ دینا اور اس کے نام سے ہمدردی چاہنا یا ہمدردی کرنا صریح لغو بات ہے۔ جس اسلام کا یہ لوگ نام لیتے ہیں اگر حقیقت میں وہ ان کے اندر زندہ ہو تو جونہی ان کے علم میں یہ بات آئے کہ اسلامی جماعت کا کوئی شخص کوئی کام اسلامی نظریے کے خلاف کر رہا ہے‘ یہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں اور اس سے توبہ کرا کے چھوڑیں۔ کسی کا مدد چاہنا تو درکنار‘ ایک زندہ اسلامی سوسائٹی میں تو کوئی شخص اصول اسلام کی خلاف ورزی کا نام تک نہیں لے سکتا لیکن آپ کی سوسائٹی میں رات دن یہی معاملہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ آپ کے اندر جاہلی قومیت آگئی ہے۔ جس چیز کو آپ اسلامی اخوت کہہ رہے ہیں یہ دراصل جاہلی قومیت کا رشتہ ہے جو آپ نے غیر مسلموں سے لے لیا ہے۔
اسی جاہلیت کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ کے اندر’قومی مفاد‘ کا ایک عجیب تصور پیدا ہوگیا ہے اور آپ اس کو بے تکلف ’اسلامی مفاد‘ بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد اسلامی مفاد یا قومی مفاد کیا چیز ہے؟ یہ کہ جو لوگ ’مسلمان‘ کہلاتے ہیں ان کا بھلا ہو‘ ان کے پاس دولت آئے‘ ان کی عزت بڑھے‘ ان کو اقتدار نصیب ہو‘ اور کسی نہ کسی طرح ان کی دنیا بن جائے۔ بلا لحاظ اس کے کہ یہ سب فائدے اسلامی نظریے اور اسلامی اصول کی پیروی کرتے ہوئے حاصل ہوں، یا خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ پیدائشی مسلمان یا خاندانی مسلمان کو آپ ’مسلمان‘ کہتے ہیں‘ چاہے اس کے خیالات اور اس کے طرز عمل میں اسلام کی صفت کہیں ڈھونڈے نہ ملتی ہو۔ گویا آپ کے نزدیک مسلمان روح کا نہیں، بلکہ جسم کا نام ہے اور صفت اسلام سے قطع نظر کرکے بھی ایک شخص کو مسلمان کہا جاسکتا ہے۔ اس غلط تصور کے ساتھ جن جسموں کا اسم ذات آپ نے مسلمان رکھ چھوڑا ہے ان کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت‘ ان کی ترقی کو آپ اسلامی ترقی‘ ان کے فائدے کو آپ اسلامی مفاد قرار دیتے ہیں‘ خواہ یہ حکومت اور یہ ترقی اور یہ مفاد سراسر اصول اسلام کے منافی ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح جرمنیت کسی اصول کا نام نہیں‘ محض ایک قومیت کا نام ہے‘ اور جس طرح ایک جرمن قوم پرست صرف جرمنوں کی سربلندی چاہتا ہے‘ خواہ کسی طریقے سے ہو‘ اسی طرح آپ نے بھی ’مسلمانیت‘ کو محض ایک قومیت بنا لیا ہے اور آپ کے مسلمان قوم پرست محض اپنی قوم کی سربلندی چاہتے ہیں، خواہ یہ سربلندی اصولاً اور عملاً اسلام کے بالکل برعکس طریقوں کی پیروی کا نتیجہ ہو۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ کیا درحقیقت آپ اس بات کو بھول نہیں گئے ہیں کہ مسلمان صرف اس بین الاقوامی پارٹی کا نام تھا جو دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خاص نظریے اور ایک عملی پروگرام لے کر اٹھی تھی؟ اس نظریے اور پروگرام کو الگ کرنے کے بعد محض اپنی شخصی یا اجتماعی حیثیت سے جو لوگ کسی دوسرے نظریے اور پروگرام پر کام کرتے ہیں ان کے کاموں کو آپ ’اسلامی‘ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جو شخص سرمایہ داری کے اصول پر کام کرتا ہو‘ اسے اشتراکی کے نام سے یاد کیا جائے؟ کیا سرمایہ دارانہ حکومت کو بھی آپ اشتراکی حکومت کہتے ہیں؟ کیا فاشستی طرز ادارہ کو آپ جمہوری طرز ادارہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اس طرح اصطلاحوں کو بے جا استعمال کرے تو آپ شاید اسے جاہل اور بے وقوف کہنے میں ذرا تأمل نہیں کریں گے، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کی اصطلاح کو بالکل بے جا استعمال کیا جارہا ہے اور اس میں کسی کو جاہلیت کی بو تک محسوس نہیں ہوتی۔
مسلمان کا لفظ خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ’اسم ذات‘ نہیں بلکہ ’اسم صفت‘ ہی ہوسکتا ہے اور ’پیرو اسلام‘ کے سوا اس کا کوئی دوسرا مفہوم سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ انسان کی اس خاص ذہنی‘ اخلاقی اور عملی صفت کو ظاہر کرتا ہے جس کا نام ’اسلام‘ ہے۔ لہٰذا آپ اس لفظ کو شخص مسلمان کے لیے اس طرح استعمال نہیں کرسکتے جس طرح آپ ہندویا جاپانی یا چینی کے الفاظ شخصِ ہندو‘ شخصِ جاپانی یا شخصِ چینی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سانام رکھنے والا جونہی اصول اسلام سے ہٹا‘ اس سے مسلمان ہونے کی حیثیت خود بخود سلب ہو جاتی ہے۔اب وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی شخصی حیثیت میں کرتا ہے۔ اسلام کا نام استعمال کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ’مسلمان کا مفاد‘ ’مسلمان کی ترقی‘، ’مسلمان کی حکومت و ریاست‘،’مسلمان کی وزارت‘، ’مسلمان کی تنظیم‘ اور ایسے ہی دوسرے الفاظ آپ صرف ان مواقع پر بول سکتے ہیں جب کہ یہ چیزیں اسلامی نظریے اور اصول کے مطابق ہوں اور اس مشن کو پورا کرنے سے متعلق ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی لفظ مسلمان کا استعمال درست نہیں۔۷۸؎ آپ ان کو جس دوسرے نام سے چاہیں‘ موسوم کریں‘ بہرحال مسلمان کے نام سے موسوم نہیں کرسکتے کیونکہ صفت اسلام سے قطع نظر کرکے مسلمان سرے سے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ آپ کبھی اس بات کا تصور نہیں کرسکتے کہ اشتراکیت سے قطع نظر کرکے کسی شخص یا قوم کا نام اشتراکی ہے اور اس معنی میں کسی مفاد کو اشتراکی مفاد یا کسی حکومت یا کسی تنظیم کو اشتراکیوں کی حکومت یا تنظیم یا کسی ترقی کو اشتراکیوں کی ترقی کہا جاسکتا ہے۔ پھر آخر مسلمان کے معاملے میں آپ نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اسلام سے قطع نظر کرکے مسلمان کسی شخص یا قوم کا ذاتی نام ہے اور اس کی ہر چیز کو اسلامی کہہ دیا جاسکتا ہے۔
اس غلط فہمی نے بنیادی طور پر اپنی تہذیب‘ اپنے تمدن اور اپنی تاریخ کے متعلق آپ کے رویے کو غلط کر دیا ہے۔ جو بادشاہتیں اور حکومتیں غیر اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی تھیں آپ ان کو ’اسلامی حکومتیں‘ کہتے ہیں۔ محض اس لیے کہ ان کے تخت نشین مسلمان تھے۔ جو تمدن قرطبہ و بغداد اور دہلی و قاہرہ کے عیش پرست درباروں میں پرورش پایا تھا‘ آپ اسے ’اسلامی تمدن‘ کہتے ہیں حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔
آپ سے جب اسلامی تہذیب کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو آپ جھٹ سے آگرہ] بھارت[ کے تاج محل کی طرف اشارہ کردیتے ہیں۔ گویا یہ ہے اس تہذیب کا سب سے زیادہ نمایاں نمونہ۔ حالانکہ اسلامی تہذیب سرے سے یہ ہے ہی نہیں کہ ایک میت کو سپرد خاک کرنے کے لیے ایکڑوں زمین مستقل طور پر گھیر لی جائے اور اس پر لاکھوں روپے کی عمارت تعمیر کی جائے۔ آپ جب اسلامی تاریخ کے مفاخر بیان کرنے پر آتے ہیں تو عباسیوں‘ سلجوقیوں اور مغلوں کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تاریخ کے نقطۂ نظر سے ان کارناموں کا بڑا حصہ آب زر سے نہیں، بلکہ سیاہ روشنائی سے جرائم کی فہرست میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کا نام ’اسلامی تاریخ‘ رکھ چھوڑا ہے‘ بلکہ آپ اسے ’تاریخ اسلام‘ بھی کہہ دیتے ہیں‘ گویا ان بادشاہوں کا نام اسلام ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ اسلام کے مشن اور اس کے اصول و نظریات کو سامنے رکھ کر اپنی گزشتہ تاریخ کا احتساب کریں‘ اور پورے انصاف کے ساتھ اسلامی حرکات کو غیر اسلامی حرکات سے ممتاز کرکے دیکھیں اور دکھائیں۔ اسلامی تاریخ کی خدمت آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی حمایت و مدافعت کریں۔ آپ کے زاویۂ نظر میں یہ کجی صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ مسلمان کی ہر چیز کو ’اسلامی‘ سمجھتے ہیں اور آپ کا گمان یہ ہے کہ جو شخص مسلمان کہلاتا ہے وہ اگر غیر مسلمانہ طریق پر بھی کام کرے تو اس کے کام کو مسلمان کاکام کہا جاسکتا ہے۔
یہی ٹیڑھا زاویۂ نظر آپ نے اپنی ملّی سیاست میں بھی اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام کے اصول و نظریات اور اس کے مشن سے قطع نظر کرکے آپ ایک قوم کو ’مسلم قوم‘ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس قوم کی طرف سے‘ یا اس کے نام سے‘ یا اس کے لیے ہر شخص اور ہر گروہ من مانی کارروائیاں کرسکتا ہے۔ آپ کے نزدیک ہر وہ شخص مسلمانوں کا نمایندہ، بلکہ ان کا لیڈر بھی بن سکتا ہے جو ’مسلمانوں کی قوم‘ سے تعلق رکھتا ہو‘ خواہ اس غریب کو اسلام کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ آپ ہر اس پارٹی کے ساتھ لگ چکنے کو تیار ہو جاتے ہیں جس کی پیروی میں آپ کو کسی نوعیت کا فائدہ نظر آئے‘ خواہ اس کا مشن اسلام کے مشن سے کتنا ہی مختلف ہو۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کو چار روٹیاں ملنے کا کوئی انتظام ہو جائے‘ خواہ اسلام کی نگاہ میں وہ حرام کی روٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ پھولے نہیں سماتے جب کسی جگہ مسلمان آپ کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا نظر آتا ہے‘ خواہ وہ اس اقتدار کو بالکل اسی طرح غیر اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو‘ جس طرح ایک غیر مسلم کرسکتا ہے۔ آپ اکثر ان چیزوں کا نام اسلامی مفاد رکھتے ہیں جو حقیقتاً غیر اسلامی ہیں‘ ان اداروں کی حمایت و حفاظت پر اپنا زور صرف کرتے ہیں جو اصول اسلام کے بالکل خلاف قائم ہوئے ہیں‘ اور ان مقاصد کے پیچھے اپنا روپیہ اور اپنی قومی طاقت ضائع کرتے ہیں جو ہرگز اسلامی نہیں ہیں۔ یہ سب نتائج اسی ایک بنیادی غلطی کے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محض ایک ’قوم‘ سمجھ لیا ہے اور اس حقیقت کو آپ بھول گئے ہیں کہ دراصل آپ ایک ’بین الاقوامی پارٹی‘ ہیں جس کا کوئی مفاد اور کوئی مقصد اپنی پارٹی کے اصولوں کو دنیا میں حکمران بنانے کے سوا نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر قوم کے بجائے پارٹی کا تصور پیدا نہ کریں گے اور اس کو ایک زندہ تصور نہ بنائیں گے‘ زندگی کے کسی معاملے میں بھی آپ کا رویہ درست نہ ہوگا۔
اِستدراک
اس مضمون کی اشاعت کے بعد متعدد اصحاب نے اس شبہے کا اظہار کیا کہ ’اسلامی جماعت‘ کو ’قوم‘ کے بجائے پارٹی کہنے سے اس امر کی گنجائش نکلتی ہے کہ وہ کسی وطنی قومیت کی جز بن کر رہے۔ جس طرح ایک قوم میں مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور اپنا الگ الگ مسلک رکھنے کے باوجود سب کی سب اس بڑے مجموعے میں شامل رہتی ہیں جس کو’قوم‘ کہا جاتا ہے‘ اسی طرح اگر مسلمان ایک پارٹی ہیں تو وہ بھی اپنے وطن کی قوم کا ایک جز بن کر رہ سکتے ہیں۔
چونکہ جماعت یا پارٹی کے لفظ کو عام طور پر لوگ سیاسی یا پولیٹیکل پارٹی کے معنی میں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ غلط فہمی پیدا ہوئی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس لفظ کا اصلی مفہوم نہیں ہے بلکہ ایک خاص معنی میں بکثرت استعمال ہونے سے پیدا ہوگیا ہے۔ اصلی مفہوم اس لفظ کا یہ ہے کہ جو لوگ ایک مخصوص عقیدے‘ نظریے‘ مسلک اور مقصد پر مجتمع ہوں وہ ایک جماعت ہیں۔ اس معنی میں قرآن نے ’حزب‘ اور ’امت‘ کے الفاظ استعمال کیے ہیں‘ اور اسی معنی میں ’جماعت‘ کا لفظ احادیث اور آثار میں مستعمل ہوا ہے اور یہی مفہوم ’پارٹی‘ کا بھی ہے۔
اب ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جس کے پیشِ نظر ایک قوم یا ملک کے مخصوص حالات کے لحاظ سے، سیاسی تدبیر کا ایک خاص نظریہ اور پروگرام ہوتا ہے۔ اس قسم کی جماعت محض ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس قوم کا جز بن کر کام کرسکتی ہے اور کرتی ہے جس میں وہ پیدا ہو۔
دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو ایک کلی نظریے اور جہانی تصور (world idea)لے کر اٹھتی ہے۔ جس کے سامنے تمام بنی نوع انسانی کے لیے بلا لحاظ قوم و وطن ایک عالم گیر مسلک ہوتا ہے، جو پوری زندگی کی تشکیل و تعمیر ایک نئے ڈھنگ پر کرنا چاہتی ہے۔ جس کا نظریہ و مسلک‘ عقائد و افکار اور اصول اخلاق سے لے کر انفرادی برتائو اور اجتماعی نظام کی تفصیلات تک ہر چیز کو اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ جو ایک مستقل تہذیب اور ایک مخصوص تمدن (civilisation) کو وجود میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ جماعت بھی اگرچہ حقیقت میں ایک جماعت ہی ہوتی ہے‘ لیکن یہ اس قسم کی جماعت نہیں ہوتی جو کسی قوم کا جز بن کر کام کر سکتی ہو۔ یہ محدود قومیتوں سے بالا تر ہوتی ہے۔ اس کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ ان نسلی و روایتی تعصبات کو توڑ دے جن پر دنیا میں مختلف قومیتیں بنتی ہیں۔ پھر یہ خود اپنے آپ کو کس طرح ان قومیتوں کے ساتھ وابستہ کرسکتی ہے؟ یہ نسلی و تاریخی قومیتوں کے بجائے ایک عقلی قومیت (rational nationality)بناتی ہے۔ جامد قومیتوں کی جگہ ایک نامی قومیت (expanding nationality)بناتی ہے۔ یہ خود ایک ایسی قومیت بنتی ہے جو عقلی و تہذیبی وحدت کی بنیاد پر روئے زمین کی پوری آبادی کو اپنے دائرے میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن ایک قومیت بننے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک جماعت ہی رہتی ہے کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مدار پیدائش پر نہیں ہوتا، بلکہ اس نظریے و مسلک کی پیروی پر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ جماعت بنی ہے۔
مسلمان دراصل اسی دوسری قسم کی جماعت کا نام ہے۔ یہ اس قسم کی پارٹی نہیں ہے جیسی پارٹیاں ایک قوم میں بنا کرتی ہیں، بلکہ یہ اس قسم کی پارٹی ہے جو ایک مستقل نظام تہذیب و تمدن (civilisation)بنانے کے لیے اٹھتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی قومیتوں کی تنگ سرحدوں کو توڑ کر عقلی بنیادوں پر ایک بڑی جہانی قومیت (world nationality)بنانا چاہتی ہے۔ اس کو ’قوم‘ کہنا اس لحاظ سے یقیناً درست ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کی نسلی یا تاریخی قومیتوں میں سے کسی قومیت کے ساتھ بھی باعتبار جذبات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ اپنے نظریۂ حیات اور فلسفۂ اجتماعی (social philosophy)کے مطابق خود اپنی تہذیب و مدنیت کی عمارت الگ بناتی ہے، لیکن اس معنی کے لحاظ سے ’قوم‘ ہونے کے باوجود یہ حقیقت میں ’جماعت‘ ہی رہتی ہے کیونکہ محض اتفاقی پیدائش (mere accident of birth)کسی شخص کو اس قوم کا ممبر نہیں بناسکتی، جب تک کہ وہ اس کے مسلک کا معتقد اور پیرو نہ ہو، اور اسی طرح کسی شخص کا کسی دوسری قوم میں پیدا ہونا اس کے لیے اس امر میں مانع بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر اس قوم میں داخل ہوجائے جب کہ وہ اس کے مسلک پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو۔ پس جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ مسلم قوم کی قومیت اس کے ایک جماعت یا پارٹی ہونے ہی کی بنا پر قائم ہے۔ جماعتی حیثیت جڑ کا حکم رکھتی ہے اور قومی حیثیت اس کی فرع ہے۔ اگر جماعتی حیثیت کو اس سے الگ کرلیا جائے اور یہ مجرد ایک قوم بن کر رہ جائے تو یہ اس کا تنزل (degeneration)ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ انسانی اجتماعات کی تاریخ میں اسلامی جماعت کی حیثیت بالکل نرالی اور انوکھی واقع ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے بدھ مت اور مسیحیت نے قومیتوں کے حدود کو توڑ کر تمام عالم انسانی کو خطاب کیا اور ایک نظریے و مسلک کی بنیاد پر عالم گیر برادری بنانے کی کوشش کی، مگر ان دونوں مسلکوں کے پاس چند اخلاقی اصولوں کے سوا کوئی ایسا اجتماعی فلسفہ نہ تھا جس کی بنیاد پر یہ تہذیب و تمدن کا کوئی کلی نظام بنا سکتے۔ اس لیے یہ دونوں مسلک کوئی عالم گیر قومیت نہ بنا سکے، بلکہ ایک طرح کی برادری (brotherhood)بنا کر رہ گئے۔ اسلام کے بعد مغرب کی سائنٹیفک تہذیب اٹھی‘ جس نے اپنے خطاب کو بین الاقوامی بنانا چاہا‘ مگر اول یوم پیدائش سے اس پر نیشنلزم کا بھوت سوار ہوگیا، لہٰذا یہ بھی عالم گیر قومیت بنانے میں ناکام ہوئی۔ اب مار کسی اشتراکیت آگے بڑھی ہے اور قومیتوں کی حدوں کو توڑ کر جہانی تصور کی بنیاد پر ایک ایسی تہذیب وجود میں لانا چاہتی ہے جو عالم گیر ہو، لیکن چونکہ ابھی تک وہ نئی تہذیب پوری طرح وجود میں نہیں آئی ہے‘ جو اس کے پیش نظر ہے‘ اس لیے ابھی تک مارکسیت بھی ایک عالم گیر قومیت میں تبدیل نہیں ہو سکی ہے۔۷۹؎ اس وقت تک میدان میں تنہا اسلام ہی ایک ایسا نظریہ و مسلک ہے جو نسلی اور تاریخی قومیتوں کو توڑ کر تہذیبی بنیادوں پر ایک عالم گیر قومیت بناتا ہے‘ لہٰذا جو لوگ اسلام کی اسپرٹ سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ہی اجتماعی ہیئت کس طرح بیک وقت قوم بھی اور پارٹی بھی ہوسکتی ہے۔ وہ دنیا کی جتنی قوموں کو جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ارکان پیدا نہ ہوتے ہوں، بلکہ بنتے ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص اٹالین پیدا ہوا ہے وہ اٹالین قومیت کا رکن ہے، اور جو اٹالین پیدا نہیں ہوا وہ کسی طرح اٹالین نہیں بن سکتا۔ ایسی کسی قومیت سے وہ واقف نہیں ہیں جس کے اندر آدمی اعتقاد اور مسلک کی بنا پر داخل ہوتا ہو‘ اور اعتقاد و مسلک کے بدل جانے پر اس سے خارج ہو جاتا ہو۔ ان کے نزدیک یہ صفت ایک قوم کی نہیں بلکہ ایک پارٹی کی ہوسکتی ہے، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نرالی پارٹی اپنی الگ تہذیب بناتی ہے‘ اپنی مستقل قومیت کا اِدّعا کرتی ہے اور کسی جگہ بھی مقامی قومیت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے پر راضی نہیں ہوتی تو ان کے لیے یہ معاملہ ایک چیستان بن کر رہ جاتا ہے۔
یہی نافہمی غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں کو بھی پیش آرہی ہے۔ مدتوں سے غیر اسلامی تعلیم و تربیت پاتے رہنے اور غیر اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے اندر ’تاریخی قومیت‘ کا جاہلی تصور پیدا ہوگیا ہے۔ یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری اصلی حیثیت ایک ایسی جماعت کی تھی جو دنیا میں ایک عالم گیر انقلاب برپا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی‘ جس کی زندگی کا مقصد اپنے نظریے کو دنیا میں پھیلانا تھا‘ جس کاکام دنیا کے غلط اجتماعی نظامات کو توڑ پھوڑ کر اپنے فلسفۂ اجتماعی کی بنیاد پر ایک اجتماعی نظام مرتب کرنا تھا۔ یہ سب کچھ بھول بھال کر انھوں نے اپنے آپ کو بس اسی قسم کی ایک قوم سمجھ لیا ہے جیسی اور بہت سی قومیں موجود ہیں۔ اب ان کی مجلسوں اور انجمنوں میں‘ ان کی کانفرنسوں اور جمعیتوں میں‘ ان کے اخباروں اور رسالوں میں‘ کہیں بھی ان کی اجتماعی زندگی کے اس مشن کا ذکر نہیں آتا، جس کے لیے ان کو دنیا بھر کی قوموں میں سے نکال کر ایک امت بنایا گیا تھا۔ اس مشن کے بجائے اب جو چیز ان کی تمام توجہات کا مرکز بنی ہوئی ہے‘ وہ ’مسلمانوں‘ کا مفاد ہے۔ مسلمانوں سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو مسلمان ماں باپ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں‘ اور مفاد سے مراد اُن نسلی مسلمانوں کا مادی و سیاسی مفاد ہے یا بدرجۂ آخر اس کلچر کا تحفظ ہے جو اُن کو آبائی ورثے میں ملا ہے ____ اس مفاد کی حفاظت اور ترقی کے لیے جو تدبیر بھی کارگر ہو‘ اس کی طرف یہ دوڑ جاتے ہیں‘ بالکل اسی طرح جس طرح مسولینی ہر اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اطالویوں کے مفاد کے لیے مناسب ہو۔ کسی اصول اور نظریے کا نہ وہ پابند ہے نہ یہ۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اطالویوں کے لیے مفید ہو‘ وہ حق ہے۔ یہی چیز ہے جس کو میں مسلمانوں کا تنزل کہتا ہوں‘ اور اسی تنزل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ تم نسلی اور تاریخی قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہو، بلکہ حقیقت میں ایک جماعت ہو‘ اور تمھاری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ اپنے اندر جماعتی احساس (partysense)پیدا کرو۔
اس جماعتی احساس کے فقدان یا خود فراموشی کے برے نتائج اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ اسی بے حسی و خود فراموشی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان ہر رہ روکے پیچھے چلنے اور ہر نظریے اور مسلک کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے‘ خواہ وہ اسلام کے نظریے اور اس کے مقاصد اور اس کے اصولوں سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو۔ وہ نیشنلسٹ بھی بنتا ہے، کمیونسٹ بھی بن جاتا ہے۔ فاشستی اصول تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی تامل نہیں ہوتا، مغرب کے مختلف اجتماعی فلسفوں اور مابعد الطبیعی افکار اور علمی نظریات میں سے قریب قریب ہر ایک کے پیرو آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں گے۔ دنیا کی کوئی سیاسی‘ اجتماعی یا تمدنی تحریک ایسی نہیں جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسلمان شریک نہ ہوں اور لطف یہ ہے کہ یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں‘ سمجھتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ ان مختلف راہوں پر بھٹکنے اور دوڑنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ’مسلمان‘ کوئی پیدائشی لقب نہیں ہے، بلکہ اسلام کی راہ پر چلنے والے کا اسم صفت ہے۔ جو شخص اسلام کی راہ سے ہٹ کر کسی دوسری راہ پر چلے‘ اس کو مسلمان کہنا اس لفظ کا بالکل غلط استعمال ہے۔مسلم نیشنلسٹ اور مسلم کمیونسٹ اور اسی قسم کی دوسری اصطلاحیں بالکل اسی طرح کی متناقض اصطلاحیں ہیں جس طرح ’کمیونسٹ مہاجن‘ اور’بدھسٹ قصائی‘ کی اصطلاحیں متناقض ہیں۔
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
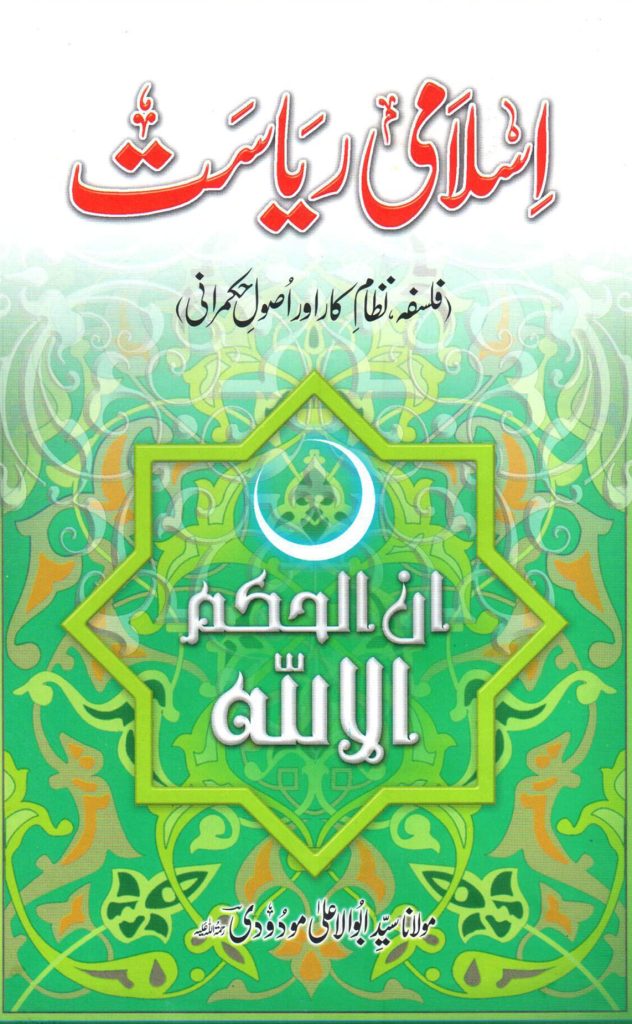

 by
by