وحشت ۵۶؎ سے مدنیت کی طرف انسان کا پہلا قدم اٹھتے ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ کثرت میں وحدت کی ایک شان پیدا ہو، اور مشترک اغراض و مصالح کے لیے متعدد افراد آپس میں مل کر تعاون اور اشتراکِ عمل کریں۔ تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس اجتماعی وحدت کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی مجموعۂ افراد کا نام ’قوم‘ ہے۔ اگرچہ لفظ ’قوم‘ اور’قومیت‘ اپنے مخصوص اصطلاحی معنوں میں حدیث العہد ہیں، مگر جس معنی پر ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود تمدن قدیم ہے۔ ’قوم‘ اور ’قومیت‘ جس ہیئت کا نام ہے وہ بابل‘ مصر‘ روم اور یونان میں بھی ویسی ہی تھی جیسی آج فرانس‘ انگلستان‘ جرمنی اور اٹلی میں ہے۔
قومیت کے غیر منفک لوازم
اس میں شک نہیں کہ قومیت کی ابتدا ایک معصوم جذبے سے ہوتی ہے‘ یعنی اس کا مقصد اول یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص گروہ کے لوگ اپنے مشترک مفاد و مصالح کے لیے عمل کریں اور اجتماعی ضروریات کے لیے ایک ’قوم‘ بن کر رہیں، لیکن جب ان میں ’قومیت‘ پیدا ہو جاتی ہے تو لازم طور پر ’عصبیت‘ کا رنگ اس میں آجاتا ہے اور جتنی جتنی ’’قومیت‘‘ شدید ہوتی جاتی ہے اسی قدر ’عصبیت‘ میں بھی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب کبھی ایک قوم اپنے مفاد کی خدمت اور اپنے مصالح کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ایک رشتۂ اتحاد میں منسلک کرے گی، یا بالفاظ دیگر‘ اپنے گرد’قومیت‘ کا حصار چن لے گی تو لازماً وہ اس حصار کے اندر والوں اور باہر والوں کے درمیان اپنے اور غیر کا امتیاز کرے گی۔ اپنے کو ہر معاملے میں غیر پر ترجیح دے گی۔ غیر کے مقابلے میں اپنے کی حمایت کرے گی۔ جب کبھی دونوں کے مفاد و مصالح میں اختلاف واقع ہوگا تو وہ اپنے کے مفاد کی حفاظت کرے گی اور اس پر غیر کے مفاد کو قربان کردے گی۔ انھی وجوہ سے ان میں صلح بھی ہوگی اور جنگ بھی، مگر رزم اور بزم دونوں میں قومیت کی حد فاصل دونوں گروہوں کے درمیان قائم رہے گی۔ اسی چیز کا نام عصبیت و حمیت ہے اور قومیت کی یہ وہ لازمی خصوصیت ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔
قومیت کے عناصرِ ترکیبی
قومیت کا قیام وحدت و اشتراک کی کسی ایک جہت سے ہوتا ہے‘ خواہ وہ کوئی جہت ہو۔ البتہ شرط یہ ہے کہ اس میں ایسی زبردست قوت رابطہ و ضابطہ ہونی چاہیے کہ اجسام کے تعدد اور نفوس کے تکثر کے باوجود وہ لوگوں کو ایک کلمہ‘ ایک خیال‘ ایک مقصد اور ایک عمل پر جمع کر دے اور قوم کے مختلف کثیر التعداد اجزا کو قومیت کے تعلق سے اس طرح بستہ و پیوستہ کر دے کہ وہ سب ایک ٹھوس چٹان بن جائیں اور افرادِ قوم کے دل و دماغ پر اتنا تسلط و غلبہ حاصل کرے کہ قومی مفاد کے معاملے میں وہ سب متحد ہوں اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہیں۔
یوں تو اشتراک اور وحدت کی جہتیں بہت سی ہونی ممکن ہیں‘ لیکن آغاز عہد تاریخ سے آج تک دنیا میں جتنی قومیتیں بنی ہیں ان سب کی تعمیر بجز ایک اسلامی قومیت کے‘ حسب ذیل اشتراکات میں سے کسی ایک قسم کے اشتراک پر ہوئی ہے اور اس عنصر کے ساتھ چند دوسرے اشتراکات بھی بطور مددگار کے شریک ہوگئے ہیں:
۱۔ اشتراکِ نسل‘ جس کو ’نسلیت‘کہتے ہیں۔
۲۔ اشتراکِ مرزبوم‘ جس کو’وطنیت‘ کہتے ہیں۔
۳۔ اشتراکِ زبان‘ جو وحدت خیال کا ایک زبردست ذریعہ ہونے کی وجہ سے قومیت کی تعمیر میں خاص حصہ لیتا ہے۔
۴۔ اشتراکِ رنگ‘ جو ایک رنگ کے لوگوں میں یک جنسی کا احساس پیدا کرتا ہے اور پھر یہی احساس ترقی کرکے ان کو دوسرے رنگ کے لوگوں سے احتراز و اجتناب پر آمادہ کر دیتا ہے۔
۵۔ معاشی اغراض کا اشتراک‘ جو ایک معاشی نظام کے لوگوں کو دوسرے معاشی نظام والوں کے مقابلے میں ممتاز کرتا ہے اور جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے معاشی حقوق و منافع کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔
۶۔ نظام حکومت کا اشتراک‘ جو ایک سلطنت کی رعایا کو مشترک نظم و نسق کے رشتے میں منسلک کرتا ہے اور دوسری سلطنت کی رعایا کے مقابلے میں حدود فاصلہ قائم کر دیتا ہے۔
قدیم ترین عہد سے لے کر آج بیسیویں صدی کے روشن زمانے تک‘ جتنی قومیتوں کے عناصرِ اصلیہ کا آپ تجسس کریں گے‘ ان سب میں آپ کو یہی مذکورہ بالا عناصر ملیں گے۔اب سے دو تین ہزار برس پہلے یونانیت‘ رومیت‘ اسرائیلیت‘ ایرانیت وغیرہ بھی انھی بنیادوں پر قائم تھیں جن پر آج جرمنیت‘ اطالویت‘ فرانسیسیت‘ انگریزیت‘ امریکنیت‘ روسیت اور جاپانیت وغیرہ قائم ہیں۔
یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ بنیادیں جن پر دنیا کی مختلف قومیتیں تعمیر کی گئی ہیں انھوں نے بڑی قوت کے ساتھ جماعتوں کی شیرازہ بندی کی ہے‘ مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابلِ انکار ہے کہ اس قسم کی قومیتیں بنی نوع انسان کے لیے ایک شدید مصیبت ہیں۔ انھوں نے عالمِ انسانی کو سیکڑوں ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور حصے بھی ایسے کہ ایک حصہ فنا کیا جاسکتا ہے، مگر دوسرے حصے میں کسی طرح تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ایک نسل دوسری نسل میں نہیں بدل سکتی۔ ایک وطن دوسرا وطن نہیں بن سکتا۔ ایک زبان کے بولنے والے دوسری زبان کے بولنے والے نہیں بن سکتے۔ ایک رنگ دوسرا رنگ نہیں بن سکتا۔ ایک قوم کی معاشی اغراض بعینہٖ دوسری قوم کی اغراض نہیں بن سکتیں۔ ایک سلطنت کبھی دوسری سلطنت نہیں بن سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو قومیتیں ان بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہیں‘ ان کے درمیان مصالحت کی کوئی سبیل نہیں نکل سکتی۔ قومی عصبیت کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے خلاف مسابقت‘ مزاحمت اور منافست ] مقابلے[ کی ایک دائمی کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں۔ ایک دوسرے کو پامال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور پھر انھی بنیادوں پر دوسری قومیتیں ایسے ہی ہنگامے برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں فساد‘ بدامنی اور شرارت کا ایک مستقل سرچشمہ ہے‘ خدا کی سب سے بڑی لعنت ہے‘ شیطان کا سب سے زیادہ کامیاب حربہ ہے جس سے وہ اپنے ازلی دشمن کا شکار کرتا ہے۔
عصبیت ِ جاہلیہ
اس قسم کی قومیت کا فطری اقتضا یہ ہے کہ وہ انسان میں جاہلانہ عصبیت پیدا کرے۔ وہ ایک قوم کو دوسری قوم سے مخالفت اور نفرت برتنے پر صرف اس لیے آمادہ کرتی ہے کہ وہ دوسری قوم کیوں ہے؟ اسے حق‘ صداقت‘ دیانت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ صرف یہ بات کہ ایک شخص کالا ہے‘ گورے کی نظر میں اسے حقیر بنا دیتی ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ ایک انسان ایشیائی ہے‘ فرنگی کی نفرتوں اور جابرانہ دراز دستیوں اور حق تلفیوں کو اس کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ آئن سٹائن جیسے فاضل کا اسرائیلی ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ جرمن اس سے نفرت کرے۔ تشکیدی ۵۷؎ کا محض سیاہ فام حبشی ہونا‘اس کو جائز کر دیتا ہے کہ یورپین کو سزا دینے کے جرم میں اس کی ریاست چھین لی جائے۔ امریکہ کے مہذب باشندوں کے لیے یہ قطعاً جائز ہے کہ وہ حبشیوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں کیونکہ وہ حبشی ہیں۔ ان کو اپنے محلوں میں نہ رہنے دیں‘ عام سڑکوں پر نہ چلنے دیں‘ تعلیمی اداروں میں تعلیم نہ پانے دیں اور ووٹ تک سے محروم رکھیں۔ جرمن کا جرمن ہونا اور فرانسیسی کا فرانسیسی ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے محاسن یکسر معائب نظر آئیں۔ سرحد کے آزاد افغانیوں کا افغانی ہونا اور دمشق کے باشندوں کا عرب ہونا‘ انگریز اور فرانسیسی کو اس کا پورا حق بخش دیتا ہے کہ وہ ان کے سروں پر طیاروں سے بم برسائیں اور ان کی آبادیوں کا قتل عام کریں‘ خواہ یورپ کے مہذب شہریوں پر اس قسم کی گولہ باری کتنی ہی وحشیانہ حرکت سمجھی جاتی ہو۔ غرض یہ جنسی امتیاز وہ چیز ہے جو انسان کو حق اور انصاف سے اندھا بنا دیتی ہے اور اس کی وجہ سے عالمگیر اصول اخلاق و شرافت بھی قومیتوں کے قالب میں ڈھل کر کہیں ظلم اور کہیں عدل‘ کہیں سچ اور کہیں جھوٹ‘ کہیں کمینگی اور کہیں شرافت بن جاتے ہیں۔
کیا انسان کے لیے اس سے زیادہ غیر معقول ذہنیت اور کوئی ہوسکتی ہے کہ وہ نالائق‘ بدکار اور شریر آدمی کو ایک لائق‘ صالح اور نیک نفس آدمی پر صرف اس لیے ترجیح دے کہ پہلا ایک نسل میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا کسی اور نسل میں؟ پہلا سپید ہے اور دوسرا سیاہ؟ پہلا ایک پہاڑ کے مغرب میں پیدا ہوا ہے اور دوسرا اس کے مشرق میں؟ پہلا ایک زبان بولتا ہے اور دوسرا کوئی اور زبان۔ پہلا ایک سلطنت کی رعایا ہے اور دوسرا کسی اور سلطنت کی؟ کیا جلد کے رنگ کو روح کی صفائی و کدورت میں بھی کوئی دخل ہے؟ کیا عقل اس کو باور کرتی ہے کہ اخلاق و اوصاف انسانی کے صلاح و فساد سے پہاڑوں اور دریائوں کا کوئی تعلق ہے‘ کیا کوئی صحیح الدماغ انسان یہ تسلیم کرسکتا ہے کہ مشرق میں جو چیز حق ہو، وہ مغرب میں باطل ہو جائے؟ کیا کسی قلب سلیم میں اس چیز کے تصور کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نیکی‘ شرافت اور جو ہر انسانیت کو رگو ں کے خون‘ زبان کی بولی‘ مولدو مسکن کی خاک کے معیار پر جانچا جائے؟ یقیناً عقل ان سوالات کا جواب نفی میں دے گی، مگر نسلیّت‘ وطنیت اور اس کے بہن بھائی نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے۔
قومیت کے عناصر پر ایک عقلی تنقید
تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو سے قطع نظر کر لیجیے۔ یہ جتنے اشتراکات آج قومیت کی بنیاد بنے ہوئے ہیں ان کو خود ان کی ذاتی حیثیت سے دیکھیے اور غور کیجیے کہ آیا یہ بجائے خود کوئی مضبوط عقلی بنیاد بھی رکھتے ہیں یا ان کی حقیقت محض سراب تخیل کی ہے۔
۱۔ نسلیت کیا ہے؟ محض خون کا اشتراک۔ اس کا نقطۂ آغاز ماں اور باپ کا نطفہ ہے جس سے چند انسانوں میں خونی رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی نطفہ پھیل کر خاندان بنتا ہے‘ پھر قبیلہ‘ پھر نسل۔ اس آخری حد یعنی نسل تک پہنچتے پہنچتے انسان اپنے اس باپ سے جس کو اس نے اپنی نسل کا مورث اعلیٰ قرار دیا ہے‘ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کی موروثیت محض ایک خیالی چیز بن جاتی ہے۔ نام نہاد ’نسل‘ کے اس دریا میں بیرونی خون کے بہت سے ندی نالے آکر مل جاتے ہیں اور کوئی صاحبِ عقل و علم انسان یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ یہ دریا خالص اسی پانی کا ہے جو اپنے اصلی سرچشمے سے نکلا تھا۔ پھر اگر اس خلط ملط کے باوجود خون کے اشتراک کی بنا پر انسان ایک ’نسل‘ کو اپنے لیے مادہ ٔاتحاد قرار دے سکتا ہے‘ تو کیوں نہ اس خون کے اشتراک کو بنائے وحدت قرار دیا جائے جو تمام انسانوں کوان کے پہلے باپ اور پہلی ماں سے ملاتا ہے اور کیوں نہ تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل کی طرف منسوب کیا جائے؟ آج جن لوگوں کو مختلف نسلوں کا بانی و مورث قرار دے لیا گیا ہے ان سب کا نسب اوپر جاکر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے مل جاتا ہے اور آخر میں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ سب ایک اصل سے ہیں۔ پھر یہ آریت اور سامیت کی تقسیم کیسی؟
۲۔ مرزبوم کے اشتراک کی حقیقت اس سے زیادہ موہوم ہے۔ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس کا رقبہ یقیناً ایک گز مربع سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس رقبے کو اگر وہ اپنا وطن قرار دے تو شاید وہ کسی ملک کو اپنا وطن نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہ اس چھوٹے سے رقبے کے گرد میلوں اور کوسوں اور بسا اوقات سیکڑوں اور ہزاروں میل تک ایک سرحدی خط کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں تک میرا وطن ہے اور اس سے باہر جو کچھ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض اس کی نظر کی تنگی ہے‘ ورنہ کوئی چیز اسے تمام رُوئے زمین کو اپنا وطن کہنے سے مانع نہیں ہے۔ جس دلیل کی بنا پر ایک مربع گز کا وطن پھیل کر ہزاروں مربع گز بن سکتا ہے‘ اسی دلیل کی بنا پر وہ پھیل کر پورا کرۂ ارضی بھی بن سکتا ہے۔ اگر آدمی اپنے زاویۂ نظر کو تنگ نہ کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ دریا اور پہاڑ اور سمندر وغیرہ جن کو اس نے محض اپنے خیال میں حدودِ فاصل قرار دے کر ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان فرق کیا ہے‘ سب کے سب ایک ہی زمین کے اجزا ہیں۔ پھر کس بنا پر اس نے دریائوں اور پہاڑوں اور سمندروں کو یہ حق دے دیا کہ وہ اسے ایک خاص خطے میں قید کر دیں؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ میں زمین کا باشندہ ہوں‘ سارا کرۂ زمین میرا وطن ہے‘ جتنے انسان ربع مسکون ۵۸؎ میں آباد ہیں ‘ میرے ہم وطن ہیں‘ اس پورے سیارے پر میں وہی پیدائشی حقوق رکھتا ہوں‘ جو اس گز بھر زمین پر مجھے حاصل ہیں جہاں میں پیدا ہوا ہوں؟
۳۔ اشتراکِ زبان کا فائدہ صرف اس قدر ہے کہ جو لوگ ایک زبان بولتے ہیں وہ باہمی تفاہم اور تبادلۂ خیالات کے زیادہ مواقع رکھتے ہیں۔ اس سے اجنبیت کا پردہ بڑی حد تک اٹھ جاتا ہے‘ اور ایک زبان بولنے والے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب تر محسوس کرتے ہیں، مگر ادائے خیال کے وسیلے کا مشترک ہونا خود خیال کے اشتراک کو مستلزم نہیں ہے۔ ایک ہی خیال دس مختلف زبانوں میں ادا ہوسکتا ہے اور ان سب کے بولنے والوں کا اس خیال میں متحد ہو جانا ناممکن ہے۔ بخلاف اس کے دس مختلف خیالات ایک زبان میں ادا ہوسکتے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اس ایک ہی زبان کے بولنے والے، ان مختلف خیالات کے معتقد ہو کر باہم مختلف ہو جائیں۔ لہٰذا وحدتِ خیال جو حقیقتاً قومیت کی جان ہے‘ اشتراکِ زبان کی محتاج نہیں ہے اور نہ اشتراکِ زبان کے ساتھ وحدثِ خیال ضروری ہے۔ پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آدمی کی آدمیت اور اس کے ذاتی حسن و قبح میں اس کی زبان کو کیا دخل ہے؟ ایک جرمن بولنے والے شخص کو ایک فرنچ بولنے والے کے مقابلے میں کیا محض اس بنا پر ترجیح دی جاسکتی ہے کہ وہ جرمن زبان بولتا ہے؟ دیکھنے کی چیز اس کا جوہر ذاتی ہے نہ کہ اس کی زبان۔ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک ملک کے انتظامی معاملات اور عام کاروبار میں وہی شخص مفید ہو سکتا ہے جو اس ملک کی زبان جانتا ہو، مگر انسانیت کی تقسیم اور قومی امتیاز کے لیے یہ کوئی صحیح بنیاد نہیں ہے۔
۴۔انسانی جماعتوں میں رنگ کا امتیاز سب سے زیادہ لغو اور مہمل چیز ہے۔ رنگ محض جسم کی صفت ہے‘ مگر انسان کے انسان ہونے کا شرف اس کے جسم کی بنا پر نہیں‘ اس کی روح‘ اس کے نفسِ ناطقہ کی بنا پر ہے‘ جس کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ پھر انسان اور انسان میں زردی اور سرخی‘ سیاہی اور سپیدی کا امتیاز کیسا؟ ہم کالی گائے اور سپید گائے کے دودھ میں کوئی فرق نہیں کرتے اس لیے کہ مقصود اس کا دودھ ہے نہ کہ اس کا رنگ۔ لیکن عقل کی بے راہ روی کا بُرا ہو کہ اس نے ہم کو انسان کی نفسی صفات سے قطع نظر کرکے اس کی جلد کے رنگ کی طرف متوجہ کر دیا۔
۵۔ معاشی اغراض کا اشتراک انسانی خود غرضی کا ایک ناجائز بچہ ہے۔ قدرت نے اس کو ہرگز پیدا نہیں کیا۔ آدمی کا بچہ کام کرنے کی قوتیں ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ جدوجہد کے لیے اسے ایک وسیع میدان ملتا ہے اور زندگی کے بے شمار وسائل اس کا استقبال کرتے ہیں، مگر وہ اپنی معیشت کے لیے صرف اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھلیں‘ بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ بند ہو جائیں۔ اسی خود غرضی میں انسانوں کی کسی بڑی جماعت کے مشترک ہو جانے سے وہ وحدت پیدا ہوتی ہے جو انھیں ایک قوم بننے میں مدد دیتی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے معاشی اغراض کا ایک حلقہ قائم کرکے اپنے حقوق و مفاد کا تحفظ کرلیا۔ لیکن جب اس طرح بہت سی جماعتیں اپنے گرد اسی قسم کے حصار کھینچ لیتی ہیں تو انسان پر اس کے اپنے ہاتھوں سے عرصۂ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی اپنی خود غرضی اس کے لیے پائوں کی بیڑی اور ہاتھ کی ہتھکڑی بن جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے رزق کے دروازے بند کرنے کی کوشش میں وہ خود اپنے رزق کی کنجیاں گم کردیتا ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ یورپ‘ امریکہ اور جاپان کی سلطنتیں اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان معاشی قلعوں کو کس طرح مسمار کریں جن کو انھوں نے خود ہی حفاظت کا بہترین وسیلہ سمجھ کر تعمیر کیا تھا۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ کسبِ معیشت کے لیے حلقوںکی تقسیم اور ان کی بنا پر قومی امتیازات کا قیام ایک غیر عاقلانہ فعل ہے؟ خدا کی وسیع زمین پر انسان کو اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کی آزادی دینے میں آخر کون سی قباحت ہے؟
۶۔نظام حکومت کا اشتراک بجائے خود ایک ناپایدار اور ضعیف البنیان چیز ہے اور اس کی بنا پر ہرگز کسی مستحکم قومیت کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ ایک سلطنت کی رعایا کو اس کی وفاداری کے رشتے میں منسلک کرکے ایک قوم بنا دینے کا خیال کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سلطنت جب تک غالب و قاہر رہتی ہے‘ رعایا اس کے قانون کی گرفت میں بندھی رہتی ہے۔ یہ گرفت جہاں ڈھیلی ہوئی مختلف عناصر منتشر ہو گئے۔ سلطنت ِ مغلیہ میں مرکزی طاقت کے کمزور ہونے کے بعد کوئی چیز ہندستان کے مختلف علاقوں کو اپنی الگ الگ سیاسی قومیتیں بنا لینے سے نہ روک سکی۔ یہی حشر سلطنت ِعثمانیہ کا ہوا۔ آخری دور میں جو ان ترک نے عثمانی قومیت کا قصر تعمیر کرنے کے لیے بہت کچھ زور لگایا، مگر ایک ٹھیس لگتے ہی سب اینٹ پتھر جدا ہوگئے۔ تازہ ترین مثال آسٹریا‘ ہنگری کی ہے۔ تاریخ سے بہت سی مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد جو لوگ سیاسی قومیتوں کی تعمیر ممکن سمجھتے ہیں وہ محض اپنے تخیل کی شادابی کے لیے مبارک باد کے مستحق ہیں۔
اس تنقید سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نسلِ انسانی میں یہ جتنی تفریقیں کی گئی ہیں، ان کے لیے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے۔ یہ صرف حسی اور مادی تفریقیں ہیں جن کا ہر دائرہ زاویۂ نظر کی ہر وسعت پرٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا قیام و بقا جہالت کی تاریکی‘ نگاہ کی محدودیت اور دل کی تنگی پر منحصر ہے۔ علم و عرفان کی روشنی جس قدرپھیلتی ہے‘ بصیرت کی رسائی جس قدر بڑھتی ہے‘ قلب میں جتنی جتنی وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے‘ یہ مادی اور حسی پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں‘ یہاں تک کہ نسلیت کو انسانیت کے لیے اور وطنیت کو آفاقیت کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ اختلاف رنگ و زبان میں جو ہر انسانی کی وحدت جلوہ گر ہوتی ہے۔ خدا کی زمین میں خدا کے سب بندوں کی معاشی اغراض مشترک پائی جاتی ہیں۔ سیاسی نظامات کے دائرے محض چند سائے نظر آتے ہیں جو آفتاب ِاقبال کی گردش سے رُوئے زمین پر چلتے پھرتے اور گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔
اسلام کا وسیع نظریہ
ٹھیک یہی بات ہے جو اسلام کہتا ہے۔ اس نے انسان اور انسان کے درمیان کسی مادی اور حسی فرق کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب انسان ایک ہی اصل سے ہیں:
خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَۃٍ وَّخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَہَا وَبَثَّ مِنْہُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۗءً النسائ4:1
خدا نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو (دنیا میں) پھیلا دیا۔
تمھارے درمیان مرزبوم اور مولد و مدفن کا اختلاف کوئی جوہری چیز نہیں ہے۔ اصل میں تم سب ایک ہی ہو۔
وَہُوَالَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَۃٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْـتَوْدَعٌ۰ۭ الانعام98:6
اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک جگہ اس کے سپرد خاک ہونے کی ہے۔
اس کے بعد نسل اور خاندان کے اختلاف کی بھی یہ حقیقت بتلا دی کہ:
يٰٓاَيُّہَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا۰ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہِ اَتْقٰىكُمْ۰ۭ الحجرات13:49
لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جائو، مگر درحقیقت معزز تو تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیز گار ہے۔
یعنی یہ شعوب و قبائل کا اختلاف محض تعارف کے لیے ہے‘ آپس کے بغض، ایک دوسرے پر تفاخر‘ ایک دوسرے سے جھگڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اس اختلاف میں انسانی اصل کی وحدت کو نہ بھول جائو۔ تم میں اگر کوئی حقیقی تفریق ہے تو وہ اخلاق و اعمال کی نیکی اور بدی کی بنا پر ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ گروہوں کی تفریق اور جماعتوں کا اختلاف خدا کا عذاب ہے جو تم کو آپس کی دشمنی کا مزہ چکھاتا ہے:
اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ۰ۭ الانعام65:6
یا تو تم کو گروہ گروہ بنا دے اور تمھیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے۔
اس گروہ بندی کو اس نے مِن جملہ ان جرائم کے قرار دیا ہے جن کی بنا پر فرعون لعنت و عذاب کا مستحق ہوا۔
اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَہْلَہَا شِيَعًا القصص 4:28
فرعون نے زمین پر تکبر کیا اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔۵۹؎
پھر کہا: زمین خدا کی ہے‘ اس نے نوعِ انسانی کو اس میں اپنی خلافت سے سرفراز کیا ہے‘ اس کی سب چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ کچھ ضروری نہیں کہ انسان ایک خطے کا بندہ بن کر رہ جائے۔ یہ وسیع زمین اس کے لیے کھلی ہوئی ہے‘ ایک جگہ اس کے لیے تنگ ہو تو دوسری جگہ چلا جائے‘ جہاں جائے گا خدا کی نعمتیں موجود پائے گا:
اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَۃً۰ۭ البقرہ30:2
(آدم کی تخلیق کے وقت خدا نے فرمایا کہ) میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ الحج65:22
کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمھارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ہے جو زمین میں ہیں۔
اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللہِ وَاسِعَۃً فَتُھَاجِرُوْا فِيْھَا۰ۭ النساء97:4
کیا اللہ کی زمین وسیع اور کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرکے چلے جاتے۔
وَمَنْ يُّھَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللہِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَۃً۰ۭ النساء100:4
جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں وافر جگہ اور کشائش پائے گا۔
آپ پورے قرآن کو دیکھ جائیے۔ اس میں ایک لفظ بھی آپ کو نسلیت یا وطنیت کی تائید میں نہ ملے گا۔ اس کی دعوت کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے۔ تمام رُوئے زمین کی انسانی مخلوق کو وہ خیر و صلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں نہ کسی قوم کی تخصیص ہے اورنہ کسی سرزمین کی۔ اس نے اگر کسی زمین کے ساتھ خاص تعلق پیدا کیا ہے تو وہ صرف مکہ کی زمین ہے‘ لیکن اس کے متعلق بھی صاف کہہ دیا کہ سَوَاۗءَۨ الْعَاكِفُ فِيْہِ وَالْبَادِ ط الحج25:22 یعنی مکہ کے اصلی باشندے اور باہر والے سب مسلمان برابر ہیں، ۶۰؎ اور جو مشرکین وہاں کے اصلی باشندے تھے، ان کے متعلق کہا کہ وہ نجس ہیں‘ ان کو وہاں سے نکال باہر کرو: اِنَّمَا الْمُشْرِکُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عَا مِھِمْ ھٰذَا۔ التوبہ 28:9 مشرکین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔
اس تصریح کے بعد اسلام میں وطنیت کا کلی استیصال ہو جاتا ہے اور درحقیقت ایک مسلمان یہی کہہ سکتا ہے کہ:
ہر ملک ملکِ ماست کہ ملک خدائے ماست
عصبیت اور اسلام کی دشمنی
اسلام جب ظاہر ہوا تو اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی نسل و وطن کے تعصبات و امتیازات تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ان تعصبات میں سب سے پیش پیش تھی۔ خاندانوں کے مفاخر اور نسبی و ذاتی و جاہتوں کے تخیّلات، ان کے اور اسلام کے درمیان شدت کے ساتھ حائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اگر خدا کی طرف سے اترتا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اترتا: وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ ھٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰي رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتَيْنِ عَظِيْمٍ۔۶۱؎ الزخرف31:43 ابوجہل سمجھتاتھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دعویٰ کرکے اپنے خاندانی مفاخر میں ایک اور فخر کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا قول تھا کہ:
ہم سے اور بنو عبدمناف سے مقابلہ تھا۔ ہم شہسواری میں ان کے حریف تھے۔ کھانے اور کھلانے میں‘ عطا اور بخشش میں ان کے برابر تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وحی آنی شروع ہوئی ہے۔ خدا کی قسم! ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصدیق نہ کریں گے۔
یہ صرف ابوجہل ہی کے خیالات نہ تھے، بلکہ تمام مشرکین قریش کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کا یہی عیب تھا کہ:
مذہب او قاطع ملک و نسب
از قریش و منکر از فضل عرب
در نگاہ او یکے بالا و پست
با غلام خویش بریک خواں نشست
قدرِ احرارِ عرب نشناختہ
با کلفتان حبش در ساختہ
احمراں با اسوداں آمیختند
آبروئے دودمانے ریختند ۶۲؎
اسی بنا پر قریش کے تمام خاندان بنی ہاشم سے بگڑ گئے اور بنی ہاشم نے بھی اسی قومی عصبیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی‘ حالانکہ ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ شعب ابی طالب میں بنی ہاشم کو اسی لیے محصور کیا گیا اور تمام قریش نے اسی وجہ سے ان سے مقاطعہ کرلیا۔ جن مسلمانوں کے خاندان کمزور تھے ان کو شدید مظالم سے تنگ آکر حبش کی جانب ہجرت کرنی پڑی اور جن کے خاندان طاقت وَر تھے وہ اپنی حق پرستی کی بنا پر نہیں، بلکہ خاندانی طاقت کی بنا پر قریش کے ظلم و ستم سے ایک حد تک محفوظ رہے۔
عرب کے یہودی، انبیائے بنی اسرائیل (علیھم السلام)کی پیشین گوئیوں کی بنا پر مدتوں سے ایک نبی کے منتظر تھے۔ انھی کی دی ہوئی خبروں کا نتیجہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شائع ہوئی تو مدینہ کے بہت سے باشندے مسلمان ہوگئے، مگر خود یہودیوں کو جس چیز نے آپؐ کی تصدیق سے روکا وہ یہی نسلی عصبیت تھی۔ ان کو اس پر اعتراض تھا کہ آنے والا نبی‘ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ اس تعصب نے ان کو یہاں تک مدہوش کر دیا کہ وہ موحدین کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھی ہوگئے۔
یہی حال نصاریٰ کا تھا۔ آنے والے نبی کے وہ بھی منتظر تھے مگر ان کو توقع تھی کہ وہ شام میں پیدا ہوگا۔ عرب کے کسی نبی کے ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ ہرقل کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا تو اس نے قریش کے تاجروں سے کہا کہ:
مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی ابھی اور آنے والا ہے، مگر یہ امید نہ تھی کہ وہ تم میں سے ہوگا۔
مقوقس مصر کے پاس جب دعوت نامہ اسلام پہنچا تو اس نے بھی یہی کہا کہ:
ابھی ایک نبی آنا باقی ہے‘ یہ مجھے معلوم ہے مگر مجھے امید تھی کہ وہ شام میں آئے گا۔
اسی تعصب کا دور دورہ عجم میں بھی تھا۔ خسرو پرویز کے پاس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامۂ مبارک پہنچا تو کس چیز نے اس کو غضب ناک کیا؟ یہی کہ ’ایک غلام قوم کا فرد اور پادشاہِ عجم کو اس طرح مخاطب کرے‘۔ وہ عرب کی قوم کو ذلیل سمجھتا تھا۔ اپنا ماتحت خیال کرتا تھا۔ یہ بات ماننے کے لیے وہ کسی طرح تیار نہ تھا کہ ایسی قوم میں کوئی حق کی طرف بلانے والا پیدا ہوگا۔
اسلام کے خلاف اس کے دشمن یہودیوں کے پاس سب سے بڑا کار گر حربہ یہی تھا کہ مسلمانوں میں قبائلی عصبیت پیدا کریں۔ اسی بنیاد پر مدینہ کے منافقین سے ان کی سازباز تھی۔ ایک مرتبہ انھوں نے جنگِ بُعَاث کا ذکر چھیڑ کر انصار کے دونوں قبیلوں ( اوس اور خزرج) میں عصبیت کی ایک ایسی آگ بھڑکائی کہ تلواریں کھنچنے کی نوبت آگئی۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ:
يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَo
آل عمران 100:3
مسلمانو! اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ تم کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں گے۔
یہی نسل و وطن کا تعصب تھا جس نے مدینہ میں قریش کے نبی کو حکمران دیکھ کر اور مہاجرین کو انصار کے باغوں اور نخلستانوں میں چلتے پھرتے دیکھ کر مدینہ کے منافقین کو آتشِ زیرِ پا کر رکھا تھا۔ عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین کہا کرتا تھا کہ:
یہ قریش کے فقیر ہمارے ملک میں آکر پھل پھول گئے ہیں۔ ان کی مثل ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر، تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔
وہ انصار سے کہتا تھا کہ ’تم نے ان کو اپنے سر چڑھا لیا ہے۔ اپنے ملک میں جگہ دی۔ اپنے اموال میں ان کو حصہ دیا۔ خدا کی قسم آج تم ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے‘۔ ان کی ان باتوں کا جواب قرآن مجید میں اس طرح دیا گیا ہے:
ہُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰي مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللہِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا۰ۭ وَلِلہِ خَزَاۗىِٕنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَہُوْنَo يَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَۃِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْہَا الْاَذَلَّ۰ۭ وَلِلہِ الْعِزَّۃُ وَلِرَسُوْلِہٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَo المنافقون 7-8:63
یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر منافقین اس کو نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم (میدان جنگ سے) مدینہ کی طرف واپس ہوئے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ حالانکہ عزت دراصل اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی ہے مگر منافقین اس بات کو نہیں جانتے۔
یہی عصبیت کا جوش تھا جس نے عبداللہ بن اُبیّ سے حضرت عائشہ ؓ پر تہمت لگوائی اور خزرج والوں کی حمایت نے اس دشمن خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیے کی سزا پانے سے بچالیا۔ ۶۳؎
عصبیت کے خلاف اسلام کا جہاد
اس بیان سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کفر و شرک کی جہالت کے بعد اسلام کی دعوت حق کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ یہی نسل و وطن کا شیطان تھا اور یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ۲۳ سالہ حیات نبویہ میں ضلالتِ کفر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو مٹانے کے لیے جہاد کیا وہ یہی عصبیتِ جاہلیہ تھی۔ آپ احادیث و سِیَر کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خون اور خاک‘ رنگ اور زبان‘ پستی اور بلندی کی تفریقوں کو مٹایا‘ انسان اور انسان کے درمیان غیر فطری امتیازات کی تمام سنگین دیواروں کو مسمار کیا اور انسان ہونے کی حیثیت سے تمام بنی آدم کو یکساں قرار دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی:
٭ لَیْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَی الْعَصَبِیَّۃِ لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَی الْعَصَبِیَّۃِ لَیْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَی الْعَصَبِیَّۃِ۔ (سنن ابی دائود، ۵۱۲۱)
جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے عصبیت پر جنگ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
آپؐ فرماتے تھے:
٭ لَیْسَ لِاَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰی اَحَدٍ اِلاَّ بِدِیْنٍ وَ تَقْوٰی اَلنَّاسُ کُلُّھُمْ بَنُوْ آٰدَمَ وَ آٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ۔
(مسند احمد تفہیم الاحادیث ششم، ص ۴۱۸)
پرہیزگاری اور دین داری کے سوا کسی اور چیز کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت نہیں ہے۔سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔
نسل‘ وطن‘ زبان اور رنگ کی تفریق کو آپؐ نے یہ کہہ کر مٹایا کہ:
۱۔ لَافَضْلَ لِعَرَبِیٍّ عَلٰی عَجَمِیٍّ وَلاَ لِعَجَمِیٍّ عَلٰی عَرَبِیٍّ کُلُّکُمْ اَبْنَائِ آٰدَمَ۔(بخاری و مسلم)
نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ عجمی کو عربی پر۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔
۲۔ لَا فَضْلَ لِعَرَبِیٍّ عَلٰی عَجَمِیٍّ وَلَا لِعَجَمِیٍّ عَلٰی عَرَبِیٍّ وَلَا لِاَبْیَضَ عَلٰی اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰی اَبْیَضَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰی۔ (زاد المعاد)
کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر‘ اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے‘ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔
۳۔ اِسْمَعُوْا وَاَطِیْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَیْکُمْ عَبْدٌ حَبَشِیٌّ کَاَنَّ رَاْسَہ‘ زَبِیْبَۃٌ۔
(بخاری کتاب الاحکام ۔ مشکوۃ ۳۴۹۳)
سنو اور اطاعت کرو چاہے تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر بنا دیا جائے جس کا سرکشمش جیسا ہو۔۶۴؎
فتح مکہ کے بعد جب تلوار کے زور نے قریش کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور اس میں پورے زور کے ساتھ یہ اعلان فرمایا:
اَلاَ کُلُّ مَاْثِرَۃٍ اَوْدَمٍ اَوْمَالٍ یُدْعٰی فَھُوَتَحْتَ قَدَمَیَّ ھَاتَیْنِ۔ (ابودائود، ترمذی)
خوب سن رکھو کہ فخر و ناز کا ہر سرمایہ،خون اور مال کا ہر دعویٰ آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے۔
یَا مَعْشَرَقُرَیْشٍ اِنَّ اللّٰہَ اَذْھَبَ عَنْکُمْ نَخْوَۃَ الْجَاھِلِیَّۃِ وَتَعَظُّمَھَا الْآٰبَائِ۔ (احمد، کنز العمال، حدیث ۱۲۹۴)
اے اہل قریش! اللہ نے تمھاری جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔
اَیُّھَا النَّاسُ کُلُّکُمْ مِنْ آٰدَمَ وَآٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَافَخْرَ لِلْاَنْسَابِ وَلَا فَخْرَ لِلْعَرَبِیِّ عَلَی الْعَجَمِیِّ وَلَا لِلْعَجَمِیِّ عَلَی الْعَرَبِیِّ اِنَّ اکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقَاکُمْ۔ (تفسیر ابن کثیر، ج۴، ص۲۱۷۔ مجمع الزوائد، ج۸، ص۸۶)
اے لوگو! تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے تھے۔ نسب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ عربی کو عجمی پر‘ عجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
عبادت الٰہی کے بعد آپؐ اپنے خدا کے سامنے تین باتوں کی گواہی دیتے تھے۔
۱۔ پہلے اس بات کی کہ’خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔‘
۲۔ پھر اس بات کی کہ ’محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔‘
۳۔ پھر اس بات کی کہ ’اللہ کے بندے سب بھائی بھائی ہیں۔ ‘ (اِنَّ الْعِبَادَ کُلُّھُمْ اِخْوَۃٌ)
اسلامی قومیت کی بنیاد
اس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ان تمام محدود مادی‘ حسی اور وہمی بنیادوں کو جن پر دنیا کی مختلف قومیتوں کی عمارتیں قائم کی گئی تھیں‘ ڈھا دیا۔ رنگ‘ نسل‘ وطن‘ زبان‘ معیشت اور سیاست کی غیر عقلی تفریقوں کو جن کی بنا پر انسان نے اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے انسانیت کو تقسیم کر رکھا تھا‘ مٹا دیا اور انسانیت کے مادے میں تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا ہم مرتبہ قرار دے دیا۔
اس تخریب کے ساتھ اسلام نے خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت کی تعمیر کی۔ اس قومیت کی بنا بھی امتیاز پر تھی‘ مگر مادی اور ارضی امتیاز پر نہیں‘ بلکہ روحانی اور جوہری امتیاز پر۔ اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی‘ جس کا نام ’اسلام‘ ہے۔ اس نے خدا کی بندگی و اطاعت‘ نفس کی پاکیزگی و طہارت‘ عمل کی نیکی اور پرہیزگاری کی طرف ساری نوعِ بشری کو دعوت دی۔ پھر کہہ دیا کہ جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے اور جو اس کو رد کر دے وہ دوسری قوم سے ہے۔ ایک قوم ایمان اور اسلام کی ہے اور اس کے سب افراد ایک امت ہیں: وَکَذٰلِکَ جَعَلْنٰکُمْ اُمَّۃً وَّسَطًا۶۵؎ اور ایک قوم کفر اور گمراہی کی ہے اور اس کے متبعین اپنے اختلاف کے باوجود ایک گروہ ہیں۔ وَاللّٰہُ لَا یَھْدِی الْقَوْمَ الْکٰفِرِیْنَ۔۶۶؎
ان دونوں قوموں کے درمیان بنائے امتیاز نسل اور نسب نہیں‘ اعتقاد اور عمل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں‘ اور دو بالکل اجنبی آدمی اسلام میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں مشترک ہوں۔
وطن کا اختلاف بھی ان دونوں قوموں کے درمیان وجۂ امتیاز نہیں ہے۔ یہاں امتیاز حق اور باطل کی بنیاد پر ہے جس کا کوئی وطن نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شہر‘ ایک محلے‘ ایک گھر کے دو آدمیوں کی قومیتیں اسلام اور کفر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہوجائیں اور ایک حبشی رشتۂ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک مراکشی کا قومی بھائی بن جائے۔
رنگ کا اختلاف بھی یہاں قومی تفریق کا سبب نہیں ہے۔ یہاں اعتبار چہرے کے رنگ کا نہیں‘ اللہ کے رنگ کا ہے اور وہی بہترین رنگ ہے۔ صِبْغَۃَ اللّٰہِ ط وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ صِبْغَۃً۔ ۶۷؎ ہوسکتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گورے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو، اور کفر کے اعتبار سے دو گوروں کی دو الگ قومیتیں ہوں۔
زبان کا امتیاز بھی اسلام اور کفر میں وجہِ اختلاف نہیں ہے۔ یہاں منہ کی زبان نہیں، محض دل کی زبان کا اعتبار ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اعتبار سے عربی اور افریقی کی ایک زبان ہوسکتی ہے اور دو عربوں کی زبانیں مختلف ہوسکتی ہیں۔
معاشی اور سیاسی نظاموں کا اختلاف بھی اسلام اور کفر کے اختلاف میں بے اصل ہے۔ یہاں جھگڑا دولتِ زر کا نہیں، دولت ایمان کا ہے، انسانی سلطنت کا نہیں خدا کی بادشاہت کا ہے۔ جو لوگ حکومتِ الٰہی کے وفادار ہیں اور جو خدا کے ہاتھ اپنی جانیں فروخت کر چکے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں خواہ ہندستان میں ہوں یا ترکستان میں، اور جو خدا کی حکومت سے باغی ہیں اور شیطان سے جان و مال کا سودا کرچکے ہیں وہ ایک دوسری قوم ہیں۔ ہم کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کس سلطنت کی رعایا ہیں اور کس معاشی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس طرح اسلام نے قومیت کا جو دائرہ کھینچا ہے وہ کوئی حسی اور مادی دائرہ نہیں، بلکہ ایک خالص عقلی دائرہ ہے۔ ایک گھر کے دو آدمی اس دائرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور مشرق و مغرب کا بُعد رکھنے والے دو آدمی اس میں داخل ہوسکتے ہیں ؎
سر عشق از عالم ارحام نیست
اوزسام و روم و شام نیست
کوکب بے شرق و غرب و بے غروب
در مدارش نے شمال و نے جنوب ۶۸؎
اس دائرے کا محیط ایک کلمہ ہے: لَآاِلٰہَ اِلاَّ اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ اسی کلمے پر دوستی بھی ہے اور اسی پر دشمنی بھی۔ اسی کا اقرار جمع کرتا ہے اور اسی کا انکار جدا کر دیتا ہے۔ جن کو اس نے جدا کر دیا ہے ان کو نہ خون کا رشتہ جمع کرسکتا ہے‘ نہ خاک کا‘ نہ زبان کا‘ نہ رنگ کا‘ نہ روٹی کا‘ نہ حکومت کا، اور جن کو اس نے جمع کر دیا ہے انھیں کوئی چیز جدا نہیں کرسکتی۔ کسی دریا‘ کسی پہاڑ‘ کسی سمندر‘ کسی زبان‘ کسی نسل‘ کسی رنگ اور کسی زر و زمین کے قضیے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسلام کے دائرے میں امتیازی خطوط کھینچ کر مسلمان اور مسلمان کے درمیان فرق کرے۔ ہر مسلمان خواہ وہ چین کا باشندہ ہو یا مراکش کا‘ گورا ہو یا کالا‘ ہندی بولتا ہو یا عربی‘ سامی ہو یا آرین‘ ایک حکومت کی رعیت ہو یا دوسری حکومت کی‘ مسلمان قوم کا فرد ہے‘ اسلامی سوسائٹی کا رکن ہے‘ اسلامی اسٹیٹ کا شہری ہے‘ اسلامی فوج کا سپاہی ہے‘ اسلامی قانون کی حفاظت کا مستحق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں ہے جو عبادات‘ معاملات‘ معاشرت‘ معیشت‘ سیاست‘ غرض زندگی کے کسی شعبے میں جنسیت یا زبان یا وطنیت کے لحاظ سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے مقابلے میں کم تریا بیش تر حقوق دیتی ہو۔
اسلام کا طریقِ جمع و تفریق
یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام نے تمام انسانی اور مادی رشتوں کو قطع کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں! اس نے مسلمانوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے‘ قطع رحم سے منع کیا ہے‘ ماں باپ کی اطاعت و فرماںبرداری کی تاکید کی ہے‘ خون کے رشتوں میں وراثت جاری کی ہے‘ خیر و صدقات اور بذل و انفاق میں ذوی القربیٰ کو غیر ذوی القربیٰ پر ترجیح دی ہے‘ اپنے اہل و عیال‘ اپنے گھر بار‘ اور اپنے مال کو دشمنوں سے بچانے کا حکم دیا ہے‘ ظالم کے مقابلے میں لڑنے کا حکم دیا ہے اور ایسی لڑائی میں جان دینے والے کو شہید قرار دیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں بلا امتیازِ مذہب ہر انسان کے ساتھ ہم دردی‘ حسنِ سلوک اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے کسی حکم کو یہ معنی نہیں پہنائے جاسکتے کہ وہ ملک و وطن کی خدمت و حفاظت سے روکتا ہے‘ یا غیر مسلم ہمسائے کے ساتھ صلح و مسالمت کرنے سے باز رکھتا ہے۔۶۹؎
یہ سب کچھ ان مادی رشتوں کی جائز اور فطری مراعات ہیں، مگر جس چیز نے قومیت کے معاملے میں اسلام اور غیر اسلام کے اصول میں فرق کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں نے انھی رشتوں پر جداگانہ قومیتیں بنالی ہیں اور اسلام نے ان کو بنائے قومیت قرار نہیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان سب تعلقات پر ترجیح دیتا ہے اور وقت پڑے تو ان میں سے ہر ایک کو اس پر قربان کر دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے:
۱۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَۃٌ حَسَـنَۃٌ فِيْٓ اِبْرٰہِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَہٗ۰ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِہِمْ اِنَّا بُرَءٰۗؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ۰ۡكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَۃُ وَالْبَغْضَاۗءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللہِ وَحْدَہٗٓ الممتحنہ60: 4
تمھارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یہ قابلِ تقلید نمونہ تھا کہ انھوں نے اپنی وطنی و نسلی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے اور تمھارے معبودوں سے جنھیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو‘ کوئی تعلق نہیں ہے‘ ہم نے تم کو چھوڑ دیا۔ ہمارے اور تمھارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہوگئی تاوقتیکہ تم ایک خدا پر ایمان نہ لائو۔
۲۔ لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَي الْاِيْمَانِ۰ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّہُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ ہُمُ الظّٰلِمُوْنَo التوبہ23:9
اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست اور محبوب نہ رکھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو محبوب رکھیں۔ تم میں سے جو کوئی ان کو محبوب رکھے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔
۳۔ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْہُمْ۰ۚ التغابن14:64
تمھاری بیویوں اور تمھاری اولاد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تمھارے دشمن ہیں‘ ان سے ہوشیار رہو۔
وہ کہتا ہے کہ اگر تمھارے دین اور تمھارے وطن میں دشمنی ہو جائے تو دین کی خاطر وطن چھوڑ کر نکل جائو۔ جو شخص دین کی محبت پر وطن کی محبت کو قربان کر کے ہجرت نہ کرے وہ منافق ہے‘ اس سے تمھارا کوئی تعلق نہیں۔فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْھُمْ اَوْلِيَاۗءَ حَتّٰي يُھَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللہِ النساء89:4
اس طرح اسلام اور کفر کے اختلاف سے خون کے قریب ترین رشتے کٹ جاتے ہیں۔ ماں‘ باپ‘ بھائی‘ بیٹے صرف اسی لیے جدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ ہم نسل قوم کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خدا سے دشمنی رکھتی ہے۔ وطن کو اس لیے خیر باد کہا جاتا ہے کہ وہاں اسلام اور کفر میں عداوت ہے۔ گویا اسلام دنیا کی ہر چیز پر مقدم ہے‘ ہر چیز اسلام پر قربان کی جاسکتی ہے اور اسلام کسی چیز پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے۔ یہی اسلام کا تعلق ہے جو ایسے لوگوں کو ملا کر بھائی بھائی بنا دیتا ہے جن کے درمیان نہ خون کا رشتہ ہے‘ نہ وطن کا‘ نہ زبان کا‘ نہ رنگ کا۔ تمام مسلمانوں کو خطاب کرکے کہا جاتا ہے:
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا۰۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللہِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۗءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِہٖٓ اِخْوَانًا۰ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰي شَفَا حُفْرَۃٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْھَا۰ۭ
آل عمران 103:3
تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں متفرق نہ ہو جائو۔ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے‘ اس نے تمھارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت (اسلام) کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ تم (آپس کی عصبیت کی بدولت) آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔
تمام غیر مسلموں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ:
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوۃَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ۰ۭ التوبہ11:9
اگر وہ کفر سے توبہ کرلیں‘ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمھارے دینی بھائی ہیں۔
اور مسلمانوں کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ:
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ۰ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَہٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَہُمْ الفتح29:48
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ نیز وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ پھیریں‘ ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں۔ جونہی کہ انھوں نے ایسا کیا ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہوگئے۔ اِلاّیہ کہ حق اور انصاف کی خاطر ان کو حلال کیا جائے۔ اس کے بعد ان کے وہی حقوق ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں اور ان پر وہی واجبات ہیں جو سب مسلمانوں پر ہیں۔ (ابودائود، کتاب الجہاد)
پھر یہی نہیں کہ حقوق اور فرائض میں مسلمان برابر ہیں اور ان میں کسی فرق و امتیاز کی گنجایش نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد نبویؐ ہے کہ:
o اَلْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ کَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُہ‘ بَعْضًا۔ (متفق علیہ)
مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک دیوار کے اجزا، جن میں سے ہر ایک دوسرے سے قوت پاتا ہے۔
اور:
o مَثَلُ الْمُؤْمِنِیْنَ فِیْ تَوَادِّھِمْ وَتَرَاحُمِھِمْ وَتَعَاطُفِھِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَکٰی مِنْہُ عُضْوٌ تَدَاعٰی لَہ‘ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّھَرِ وَالْحُمّٰی۔(متفق علیہ۔ مشکوٰۃ)
آپس کی محبت اور رحمت و مہربانی میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کے لیے بے خواب و بے آرام ہو جاتا ہے۔
ملت ِ اسلامیہ کے اس جسمِ نامی کو رسولؐ اللہ نے ’جماعت‘ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کے متعلق آپؐ کا فرمان ہے:
۱۔ یَدُ اللّٰہِ عَلَی الْجَمَاعَۃِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِی النَّارِ۔ (ترمذی ۲۱۶۷)
جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو اس سے بچھڑا وہ آگ میں گیا۔
۲۔ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَۃَ شِبْرًا خَلَعَ رِبْقَۃَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِہٖ۔ ( احمد و ابودائود۔ مشکوٰۃ)
جو ایک بالشت بھر بھی جماعت سے جدا ہوا اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔
اسی پر بس نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ:
مَنْ اَرَادَ اَنْ یُّفَرِّقْ جَمَاعَتَکُمْ فَاقْتُلُوْہُ۔ (مسلم۔ مشکوۃ ۳۵۰۷)
جو تمہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کو قتل کردو۔
مَنْ اَرَادَاَنْ یُّفَرِّق اَمْرَ ھٰذِہِ الْاُمَّۃِ وَھِیَ جَمِیْعٌ فَاضْرِبُوْہُ بِالسَّیْفِ کَائِنًا مَنْ کَانَ۔
(مسلم۔مشکوۃ۳۵۰۷)
جو کوئی اس امت کے بندھے ہوئے رشتے کو پارہ پارہ کرنے کا ارادہ کرے‘ اس کی تلوار سے خبرلو‘ خواہ وہ کوئی ہو۔
اسلامی قومیت کی تعمیر کس طرح ہوئی؟
اس جماعت میں جس کی شیرازہ بندی اسلام کے تعلق کی بنا پر کی گئی تھی خون اور خاک‘ رنگ اور زبان کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس میں سلمان ؓ ایرانی تھے جن سے ان کا نسب پوچھا جاتا‘ تو فرماتے کہ سلمان بن اسلام۔ حضرت علیؓ ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ سَلْمَانُ مِنَّا اَھْلَ الْبَیْتِ ’سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں‘۔اس میں باذان بن ساسان اور ان کے بیٹے شہر بن باذان تھے جن کا نسب بہرام گور سے ملتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باذانؓ کو یمن کا اور ان کے صاحبزادے کو صنعا کا والی مقرر فرمایا تھا۔ اس جماعت میں بلال حبشیؓ تھے جن کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بِلَالُ سَیِّدُنَا وَمَوْلَاسَیِّدِنَا بلالؓ ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے۔اس جماعت میں صہیبؓ رومی تھے جنھیں حضرت عمرؓ نے اپنی جگہ نماز میں امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اس میں حضرت ابوحذیفہؓ کے غلام سالم ؓ تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں خلافت کے لیے انھی کو نامزد کرتا۔ اس میں زید بن حارثہ ؓ ایک غلام تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھوپھی کی بیٹی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بیاہ دیا تھا۔ اس میں حضرت زیدؓ کے بیٹے اسامہؓ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لشکر کا سردار بنایا تھا‘ جس میں حضرت ابوبکر صدیق ؓ‘ حضرت عمر فاروق ؓ‘ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ؓ جیسے جلیل القدر صحابہ شریک تھے۔ انھی اسامہؓ کے متعلق حضرت عمرؓ اپنے بیٹے عبداللہؓ سے فرماتے ہیں کہ:اسامہؓکا باپ تیرے باپ سے افضل تھا اور اسامہؓخود تجھ سے افضل ہے۔
مہاجرین کا اُسوہ
اس جماعت نے اسلام کے تبر سے عصبیت کے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا جو نسل اوروطن‘ رنگ اور زبان وغیرہ کے نام سے موسوم ہیں اور جن کی پرستش قدیم جاہلیت سے جدید جاہلیت کے زمانے تک دنیا میں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وطن مکہ کو چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے یہ معنی نہ تھے کہ آپؐ کو اور مہاجرین کو اپنے وطن سے وہ فطری محبت نہ تھی جو انسان کو ہوا کرتی ہے۔ مکہ کو چھوڑتے وقت آپؐ نے فرمایا تھا کہ: اے مکہ! تو مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔
حضرت بلالؓ جب مدینہ جا کر بیمار ہوئے تو مکہ کی ایک ایک چیز کو یاد کرتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ حسرت بھرے اشعار آج تک مشہور ہیں:
اَلاَ لَیْتَ شِعْرِیْ ھَلْ اَبِیْتَنَّ لَیْلَۃً
بِفَخْ وَحَوْلِیْ اِذْخَرٌ وَ جَلِیْل‘
وَھَلْ اَرِدَنَّ یَوْمًا مِیَاہَ مَجَنَّہْ
وَھَلْ تَبْدُوَنْ لِیْ شَامَۃُ وَطَفِیْل‘
(البدایہ و النہایۃ، ج۳، ص۲۲)
کاش! مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں (کبھی کوئی) رات مقام فخ میں گزاروں گا اور میرے گرد اِذخر (خوشبودار گھاس) اور جلیل (بابونہ کے پودے) ہوں گے؟
اور کیا میں کسی دن مَجِنَّہ (نامی جگہ) کے گھاٹ پر بھی وارد ہوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل (مقام اور پہاڑ) نظر آئیں گے؟
مگر اس کے باوجود حبّ وطن نے ان بزرگوں کو اسلام کی خاطر ہجرت کرنے سے باز نہ رکھا۔ ۷۰ ؎
انصار کا طرز عمل
دوسری طرف اہل مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو سر آنکھوں پر بٹھایا اور اپنے جان و مال خدمت اقدس میں پیش کر دیے۔ اسی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو یہ ایسے بھائی بھائی بنے کہ مدتوں ان کو ایک دوسرے کی میراث ملتی رہی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس توارث کو بند کیا۔ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُھُمْ اَوْلٰی بِبَعْضٍ۷۱؎ انصار نے اپنے کھیت اور باغ آدھے آدھے تقسیم کرکے اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیے اور جب بنو نضیر کی زمینیں فتح ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ زمین بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجیے۔ یہی ایثار تھا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے:وَیُؤْثِرُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِھِمْ وَلَوْکَانَ بِھِمْ خَصَاصَۃٌ۷۲؎ حضرت عبداللہ بن عوفؓ اور حضرت سعد بن ربیع انصاریؓ کے درمیان مواخاۃ کرائی گئی تو حضرت سعدؓ اپنے دینی بھائی کو آدھا مال دینے اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر ان سے بیاہ دینے پر آمادہ ہوگئے۔ عہدِ رسالت کے بعد جب مہاجرین پیہم منصب خلافت پر سرفراز ہوئے تو کسی مدنی نے یہ نہ کہا کہ تم غیر ملکیوں کو ہمارے ملک پر حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ نے مدینہ کے نواح میں مہاجرین کو جاگیریں دیں اور کسی انصاری نے اس پر زبان تک نہ ہلائی۔
رشتۂ دین پر مادی علائق کی قربانی
پھر جنگ بدر اور جنگ احد میں مہاجرین مکہ دین کی خاطر خود اپنے رشتہ داروں سے لڑے۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنے بیٹے عبدالرحمان پر تلوار اٹھائی۔ حضرت حذیفہؓ نے اپنے باپ ابوحذیفہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں کے خون میں ہاتھ رنگے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباسؓ ‘ چچا زاد بھائی عقیلؓ ‘ داماد ابو العاص ؓ بدر میں گرفتار ہوئے اور عام قیدیوں کی طرح رکھے گئے۔ حضرت عمرؓتو یہاں تک آمادہ ہوگئے تھے کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر شخص خود اپنے عزیز کو قتل کرے۔
فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قبیلہ اور غیر علاقہ والوں کو لے کر خود اپنے قبیلے اور اپنے وطن پر حملہ آور ہوئے اور غیروں کے ہاتھوں اپنوں کی گردنوں پر تلوار چلوائی۔ عرب کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ کوئی شخص خود اپنے قبیلے اور اپنے وطن پر غیر قبیلہ والوں کو چڑھا لائے اور وہ بھی کسی انتقام یا زر و زمین کے قضیے کی بنا پر نہیں‘ بلکہ محض ایک کلمۂ حق کی خاطر۔ جب قریش کے اوباش مارے جانے لگے تو ابو سفیان نے آکر عرض کیا کہ: یارسولؐ اللہ! قریش کے نونہال کٹ رہے ہیں۔ آج کے بعد قریش کا نام و نشان نہ رہے گا۔ رحمۃللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اہل مکہ کو امان دے دی۔ انصار سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی قوم کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ انھوں نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر آدمی ہی تو ہیں، اپنے خاندان والوں کا پاس کر ہی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر پہنچی تو انصار کو جمع کیا اور فرمایا:مجھے خاندان والوں کی محبت نے ہرگز نہیں کھینچا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسولؐ ہوں۔ اللہ کے لیے تمھارے پاس ہجرت کرکے جا چکا ہوں۔ اب میرا جینا تمھارے ساتھ ہے اور مرنا تمھارے ساتھ۔ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا‘ اسے لفظ بلفظ سچا کرکے دکھا دیا، باوجودیکہ مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ علت باقی نہ رہی تھی جس کی بنا پر حضور اکرمؐ ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، مگر آپؐ نے مکہ میں قیام نہ فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر کسی وطنی یا انتظامی جذبے کے تحت حملہ نہ کیا تھا‘ بلکہ محض اعلائے کلمۃ الحق مقصود تھا۔
اس کے بعد جب ہوازن اور ثقیف کے اموال فتح ہوئے تو پھر وہی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے قریش کے نو مسلموں کو زیادہ حصہ دیا۔ انصار کے بعض نوجوان سمجھے یہ قومی پاس داری کی وجہ سے ہے۔ انھوں نے بگڑ کر کہا کہ:خدا‘ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، وہ قریش کو دیتے ہیں اور ہم کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اب تک ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔‘‘ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جمع کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ محض ان کی تالیفِ قلب مقصود ہے۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائو؟
غزوۂ بنی المصطلق میں ایک غفاری اور ایک عوفی میں جھگڑا ہوگیا۔ غفاری نے عوفی کو تھپڑ مارا۔ بنی عوف انصار کے حلیف تھے۔ اس لیے عوفی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا۔ بنی غِفار مہاجرین کے حلیف تھے‘ اس لیے غفاری نے مہاجرین کو آواز دی۔ قریب تھا کہ فریقین کی تلواریں کھنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپؐ نے فریقین کو بلا کر فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار تھی جو تمھاری زبانوں سے نکل رہی تھی؟ (مَالَکُمْ وَلِدَعْوَۃِ الْجَاھِلِیَّۃِ) ۔انھوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے انصاری کو مارا ہے۔ آپؐ نے فرمایا:تم اس جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو۔ یہ بڑی گھنائونی چیز ہے۔
اس غزوے میں مدینہ کا مشہور قوم پرست لیڈر عبداللہ بن اُبیّ بھی شریک تھا۔ اس نے جو سنا کہ مہاجرین کے حلیف نے انصار کے حلیف کو مارا ہے تو کہا کہ:
یہ ہمارے ملک میں آکر پھَل پُھول گئے ہیں اور اب ہمارے ہی سامنے سر اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تجھی کو پھاڑ کھائے۔ بخدا مدینہ واپس پہنچ کر جو ہم میں سے عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔
پھر اس نے انصار سے کہا کہ:’یہ تمھارا ہی کیا دھرا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی اور اپنے اموال ان پر بانٹ دیے۔ خدا کی قسم! آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ ہوا کھاتے نظر آئیں گے۔‘
یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں تو آپؐ نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ ؓ کو بلا کر فرمایا کہ تمھارا باپ یہ کہتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے غایت درجہ محبت رکھتے تھے، اور ان کو فخر تھا کہ خزرج میں کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا، مگر یہ قصہ سن کر انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم ہو تو میں اس کا سر کاٹ لائوں۔ آپؐ نے فرمایا: نہیں۔ پھر جب جنگ سے واپس ہوئے تو مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہؓ اپنے باپ کے آگے تلوار سونت کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ :’تو مدینہ میں گھس نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اب تجھے معلوم ہو کہ عزت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔‘ اس پر ابن اُبَیّ چیخ اٹھا کہ لو سنو اے اہل خزرج! اب میرا بیٹا مجھ کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ لوگوں نے آکر حضرت عبداللہؓ کو سمجھایا، مگر انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ مدینہ کے سائے میں بھی پناہ نہیں لے سکتا۔آخر کار لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ جاکر عبداللہ سے کہو کہ اپنے باپ کو گھر میں جانے دے۔ جب عبداللہ نے یہ فرمان مبارک سنا تو تلوار رکھ دی اور کہا کہ ان کا حکم ہے تو اب یہ جاسکتا ہے۔۷۳؎
بنو قینقاع پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عبادہ بن الصامت ؓ کو ان کے معاملے میں حَکم بنایا گیا۔ انھوں نے فیصلہ دیا کہ اس پورے قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ لوگ حضرت عبادہ کے قبیلے خزرج کے حلیف تھے‘ مگر انھوں نے اس تعلق کا ذرہ برابر خیال نہ کیا۔ اس طرح بنوقریظہ کے معاملے میں اوس کے سردار سعد بن معاذ ؓ کو حَکم بنایا گیا اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے‘ عورتوں اور بچوں کو سبایا ] قیدی[ اور ان کے اموال کو غنیمت قرار دیا جائے۔ اس معاملے میں حضرت سعدؓ نے ان حلیفانہ تعلقات کا ذرا خیال نہ کیا جو اوس اور بنوقریظہ کے درمیان مدت سے قائم تھے، حالانکہ عرب میں حلف کی جو اہمیت تھی وہ سب کو معلوم ہے اور مزید برآں یہ لوگ صدیوں سے انصار کے ہم وطن تھے۔
جمعیت ِ اسلامیہ کی اصلی رُوح
ان شواہد سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی قومیت کی تعمیر میں نسل و وطن اور زبان و رنگ کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس عمارت کو جس معمار نے بنایا ہے اس کا تخیل ساری دنیا سے نرالا تھا۔ اس نے تمام عالم انسانی کے مواد خام پر نظر ڈالی۔ جہاں جہاں سے اس کو اچھا اور مضبوط مسالہ ملا اس کو چھانٹ لیا۔ ایمان اور عمل صالح کے پختہ ہونے سے ان متفرق اجزا کو پیوستہ کر دیا اور ایک عالمگیر قومیت کا قصر تعمیر کیا جو سارے کرۂ ارضی پر چھایا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کا قیام و دوام منحصر ہے اس پر کہ اس کے تمام مختلف الاصل‘ مختلف الشکل‘ مختلف المقام اجزا اپنی جدا جدا اصلیتوں کو بھول کر صرف ایک اصل کو یاد رکھیں‘ اپنے جدا جدا رنگ چھوڑ کر ایک رنگ میں رنگ جائیں‘ اپنے الگ الگ مقاموں سے قطع نظر کرکے ایک مخرج صدق سے نکلیں اور ایک مدخل صدق میں داخل ہو جائیں۔ یہی وحدت ملی اس بنیان مرصوص کی جان ہے۔ اگر یہ وحدت ٹوٹ جائے‘ اگر اجزائے ملت میں اپنی اصلوں اور نسلوں کے جدا جدا ہونے‘ اپنے وطن اور مقام کے مختلف ہونے‘ اپنے رنگ و شکل کے متنوع ہونے اور اپنی اغراضِ دنیوی کے متضاد ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو اس عمارت کی دیواریں پھٹ جائیں گی اور اس کی بنیادیں ہل جائیں گی اور اس کے تمام اجزا پارہ پارہ ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک سلطنت میں کئی سلطنتیں نہیں بن سکتیں اسی طرح ایک قومیت میں کئی قومیتیں نہیں بن سکتیں۔ اسلامی قومیت کے اندر نسلی‘ وطنی، لسانی اورلونی قومیتوں کا جمع ہونا قطعاً محال ہے۔ ان دونوں قسم کی قومیتوںمیں سے ایک ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ:
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
پس جو مسلمان ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے اسے تمام قومیتوں کے احساس کو باطل اور سارے خاک و خون کے رشتوں کو قطع کرنا پڑے گا اور جو ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہتا ہے اس کے متعلق ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ اسلام اس کے قلب و روح میں نہیں اترا۔ جاہلیت اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ آج نہیں تو کل وہ اسلام سے چھوٹے گا اور اسلام اس سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری زمانے میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا تھا وہ یہی تھا کہ کہیں مسلمانوں میں جاہلی عصبیتیں پیدا نہ ہو جائیں اور ان کی بدولت اسلام کا قصرِ ملت پارہ پارہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے کہ:
لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِیْ کُفَّارًا یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ(بخاری‘ کتاب الفتن۔ ترمذی ۲۱۹۳)
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم پھر کفر کی طرف پلٹ کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔
اپنی زندگی کے آخری حج، حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو عرفات کے خطبے میں عام مسلمانوں کو خطاب کرکے فرمایا:
سن رکھو کہ! امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم ؑ کی اولاد سے ہو، اور آدم ؑ مٹی سے تھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جاہلیت کے سب دعوے باطل کر دیے گئے۔ اب تمھارے خون اور تمھاری عزتیں اور تمھارے اموال ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج حج کا دن تمھارے اس مہینے، تمھارے اس شہر میں حرام ہے۔
پھر منیٰ میں تشریف لے گئے تو اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ اس تقریر کو دہرایا اور اس پر اضافہ کیا:
دیکھو! میرے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔
عنقریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ وہاں تمھارے اعمال کی تم سے باز پرس ہوگی۔
سنو! اگر کوئی نکٹا حبشی بھی تمھارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی بات ماننا اور اطاعت کرنا۔
یہ ارشاد فرما کر پوچھا کہ:’کیا میں نے تم کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے؟‘ لوگوں نے کہا: ہاں! یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا: اے خدا ‘ گواہ رہیو، اور لوگوں سے کہا کہ: جو موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔۷۴؎
حج سے واپس ہو کر شہدائے احد کے مقام پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو خطاب کرکے فرمایا:
مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مگر ڈرتا اس سے ہوں کہ کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جائو اور آپس میں لڑنے نہ لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جائو گے جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔
اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ
یہ فتنہ جس کے ظاہر ہونے کا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا حقیقت میں ویسا ہی مہلک ثابت ہوا، جیسا آپؐ نے فرمایا تھا۔ قرنِ اول سے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر جو تباہی بھی نازل ہوئی ہے اسی کی بدولت ہوئی ہے۔ وصالِ نبویؐ کے چند ہی برس بعد ہاشمی اور اموی عصبیت کا فتنہ اٹھا، اور اس نے اسلام کے اصلی نظام سیاست کو ہمیشہ کے لیے درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے عربی‘ عجمی اور ترکی عصبیت کی شکل میں ظہور کیا اور اسلام کی سیاسی وحدت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر مختلف ممالک میں جو مسلمان سلطنتیں قائم ہوئیں ان سب کی تباہی میں سب سے زیادہ اسی فتنے کا ہاتھ تھا۔ قریب ترین زمانے میں دو سب سے بڑی مسلمان سلطنتیں ہندستان اور ترکی کی تھیں۔ ان دونوں کو اسی فتنے نے تباہ کیا۔ ہندستان میں مغل اور ہندستانی کی تفریق نے سلطنتِ مغلیہ کو ختم کیا اور ترکی میں ترک‘ عرب اور کُرد کی تفریق تباہی کی موجب ہوئی۔
اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کردیکھ جائیے۔ جہاں کوئی طاقت ور سلطنت آپ کو نظر آئے گی اس کی بنیاد میں آپ کو بلا امتیاز جنسیت مختلف نسلوں اور مختلف قوموں کا خون ملے گا۔ ان کے مدبر‘ ان کے سپہ سالار‘ ان کے اہل قلم‘ ان کے اہل سیف‘ سب کے سب مختلف الاجناس پائے جائیں گے۔ آپ عراقی کو افریقہ میں‘ شامی کو ایران میں‘ افغانی کو ہندستان میں مسلمان حکومتوں کی اسی جاں بازی‘ دیانت‘ صداقت اور امانت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے جس سے وہ خود اپنے وطن کی خدمت کرتا۔ مسلمان سلطنتیں کبھی اپنے مردانِ کار کی فراہمی میں کسی ایک ملک، یا ایک نسل کے وسائل پر منحصر نہیں رہیں۔ ہر جگہ سے قابل دماغ اور کار پرداز ہاتھ ان کے لیے جمع ہوئے اور انھوں نے ہر دارالاسلام کو اپنا وطن اور گھر سمجھا، مگر جب نفسانیت‘ خود غرضی اور عصبیت کا فتنہ اٹھا‘ اور مسلمانوں میں مرزبوم اور رنگ و نسل کے امتیازات نے راہ پائی‘ تو وہ ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگے‘ دھڑے بندیوں اور سازشوں کا دور دورہ ہوا۔ جو قوتیں دشمنوں کے خلاف صرف ہوتی تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے لگیں‘ مسلمانوں میں خانہ جنگی برپا ہوئی اور بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں صفحۂ ہستی سے مٹ گئیں۔
مغرب کی اندھی تقلید
آج مغربی قوموں سے سبق سیکھ کر ہر جگہ کے مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ عرب عربیت پر ناز کر رہا ہے۔ مصری کو اپنے فراعنہ یاد آرہے ہیں۔ ترک اپنی ترکیت کے جوش میں چنگیز خاں اور ہلاکو سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ ایرانی اپنی ایرانیت کے جوش میں کہتا ہے کہ یہ محض عرب امپیریلزم کا زور تھا کہ حسین ؓ اور علیؓ ہمارے ہیرو بن گئے‘ حالانکہ حقیقت میں ہمارے قومی ابطال تو رستم و اسفند یار تھے۔ ہندستان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہندستانی قومیت سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو آب زمزم سے قطع تعلق کرکے آب گنگا سے وابستگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھیم اور ارجن کو اپنا قومی ہیرو قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایسے بھی جنھیں ارض مکہ تو بھولے سے بھی یاد نہیں آتی لیکن ٹیکسلا‘ موہن جوداڑو‘ اور ہڑپا سے اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے وہ شب و روز بے چین رہتے ہیں، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان نادانوں نے نہ اپنی تہذیب کو سمجھا ہے اور نہ مغربی تہذیب کو۔ اصول اور حقائق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ محض سطح بیں ہیں اور سطح پر جو نقوش ان کو زیادہ نمایاں اور زیادہ خوش رنگ نظر آتے ہیں انھی پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جو چیز مغربی قومیت کے لیے آبِ حیات ہے‘ وہی چیز اسلامی قومیت کے لیے زہر ہے۔ مغربی قومیتوں کی بنیاد نسل و وطن اور زبان و رنگ کی وحدت پر قائم ہوئی ہے‘ اس لیے ہر قوم مجبور ہے کہ ہر اس شخص سے اجتناب کرے جو اس کا ہم قوم‘ ہم نسل‘ ہم زبان نہ ہو‘ خواہ وہ اس کی سرحد سے ایک ہی میل کے فاصلے پر کیوں نہ رہتا ہو۔ وہاں ایک قوم کا آدمی دوسری قوم کا سچا وفادار نہیں ہوسکتا۔ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کا سچا خادم نہیں بن سکتا۔ کوئی قوم کسی دوسری قوم کے فرد پر یہ اعتماد نہیں کرسکتی کہ وہ اس کے مفاد کو اپنی قوم کے مفاد پر ترجیح دے گا، مگر اسلامی قومیت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، یہاں قومیت کی بنیاد نسل و وطن کے بجائے اعتقاد و عمل پر رکھی گئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان ہر جنسی امتیاز کے بغیر ایک دوسرے کے شریکِ حال اور معاون ہیں۔ ایک ہندی مسلمان مصر کا ویسا ہی وفادار شہری بن سکتا ہے جیسا کہ وہ خود ہندستان کا ہے۔ ایک افغانی مسلمان شام کی حفاظت کے لیے اسی جاں بازی کے ساتھ لڑ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خود افغانستان کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے ایک ملک کے مسلمان اور دوسرے ملک کے مسلمان میں جغرافی یا نسلی تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔ اس معاملے میں اسلام کے اصول اور مغرب کے اصول ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ جو وہاں سبب قوت ہے وہ یہاں عین سبب ضعف ہے اور جو یہاں مایۂ حیات ہے وہ وہاں بعینہٖ سِمِ ّ قاتل ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو کس خوبی کے ساتھ بیا ن کیا ہے؎
اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمیؐ
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
بعض لوگ اس خیالِ خام میں مبتلا ہیں کہ وطنی یا نسلی قومیت کے احساسات پیدا ہونے کے بعد بھی اسلامی قومیت کا رشتہ مسلمانوں کے درمیان باقی رہ سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے نفس کو یہ کہہ کر دھوکا دیتے ہیں کہ یہ دونوں قسم کی قومیتیں ساتھ ساتھ چلیں گی‘ ایک سے دوسری پر آنچ نہ آئے گی‘ اور ہم ان دونوں کے فوائد جمع کرلیں گے۔ لیکن یہ محض جہل اور قلتِ فکر کا کرشمہ ہے۔ جس طرح خدا نے ایک سینے میں دو قلب نہیں رکھے اسی طرح ایک قلب میں دو قومیتوں کے متضاد اور متصادم جذبات کو جمع کرنے کی گنجائش بھی نہیں رکھی ہے۔ احساس قومیت کا لازمی نتیجہ اپنے اور غیر کا امتیاز ہے۔ اسلامی قومیت کے احساس کا فطری مقتضا یہ ہے کہ آپ مسلم کو اپنا اور غیر مسلم کو غیر سمجھیں، اور وطنی یا نسلی قومیت کے احساس کا طبعی اقتضا یہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کو اپنا سمجھیںجو آپ کا ہم وطن یا ہم نسل ہو، اور اُس کو غیر سمجھیں جو دوسرے ملک یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اب کوئی صاحب عقل ہمیں سمجھا دے کہ دونوں احساس ایک جگہ کیسے جمع ہوسکتے ہیں؟ کیونکر ممکن ہے کہ آپ اپنے غیر مسلم ہم وطن کو اپنا بھی سمجھیں اور غیر بھی؟ اور غیر وطنی مسلمان سے بعید بھی ہوں اور قریب بھی؟ ھَلْ یَجْتَمِعَانِ مَعًا؟ اَلَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ۷۵؎
پس یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں ہندیت‘ ترکیت‘ افغانیت‘ عربیت اور ایرانیت کے احساسات کا پیدا ہونا اسلامی قومیت کا احساس مٹنے اور اسلامی وحدت کے پارہ پارہ ہونے کو مستلزم ہے اور یہ نتیجہ محض عقلی نہیں ہے بلکہ بارہا مشاہدے میں آچکا ہے۔ مسلمانوں میں جب کبھی وطنی یا نسلی تعصبات پیدا ہوئے تو مسلمان نے مسلمان کا گلا ضرور کاٹا اور لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِیْ کُفَّارًا یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (ترمذی ‘ ۲۱۹۳) ۷۶؎ کے اندیشۂ نبویؐ کی تصدیق کرکے ہی چھوڑی۔ لہٰذا وطنیت کے داعیوں کو اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور دنیا کو دھوکا نہ دیں، بلکہ جو کچھ کریں یہ جان کر کریں کہ وطنی قومیت کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عین ضد ہے۔
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
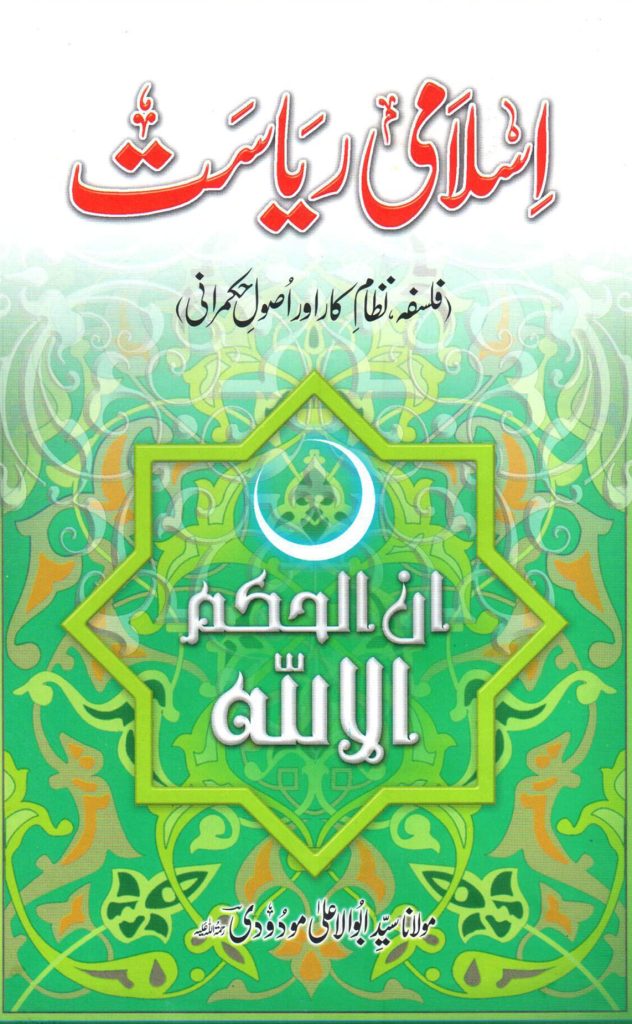

 by
by