اب ہمیں اپنی دوسری تنقیخ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جس آزادی کے لیے یہ قوم پرست حضرات لڑ رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اور کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نوعیت کی آزادی کس درجہ میں بھی ہمارے لیے مطلوب یا مفید ہو سکتی ہے؟ اس تنقیخ کو ہم دو حصوںمیں تقسیم کریں گے۔ ایک یہ کہ اس آزادی کا مطمح نظر کیا ہے؟ یعنی موجودہ حکومت کو ہٹا کر یہ کس قسم کی حکومت کن اصولوں پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ خود اس جنگ ِ آزادی کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی یہ انقلابی ذرائع سے کامل انقلاب چاہتی ہے‘ یا نیم انقلابی نیم دستوری ذرائع سے بتدریج ایک نظامِ حکومت کو گرانا اور دوسرا نظامِ حکومت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ پہلے حصہ کو ہم مقدّم رکھیں گے‘ اور دوسرے حصہ سے آخر میں بحث کریں گے۔
جو لوگ اس وقت آزادی وطن کے علم بردار بنے ہوئے ہیں ان کے مطمح نظر کو سمجھنے کے لیے تمہید کے طور پر ایک مختصر تاریخی بیان ضروری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے تخیلات کا اصلی ماخذ اور ان کے جذبات حریّت طلبی کا اصلی محرک کیا ہے۔
یہ ہر شخص جانتا ہے‘ کہ ہندستان کی موجودہ وطنی تحریک براہِ راست انگریزی تعلیم سے پیدا ہوئی ہے۔ مخالف اور موافق دونوں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انگریزی حکومت کی قائم کی ہوئی یونی ورسٹیوں میں ہندستانیوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہاں یہ تاریخ، سیاسیات اور معاشیات سے روشناس ہوئے۔ا نگریزی زبان کے توسط سے مغربی افکار ان تک پہنچے اور ان میں آہستہ آہستہ وہ سیاسی شعور پیدا ہوا جو حکومت خوداختیاری کی خواہش کا مورث ہوا کرتاہے۔ تقریبا پچاس سال تک ان جدید اثرات کے تحت پرورش پانے کے بعد جب ان کے اندر سیاسی اختیارت حاصل کرنے کا جذبہ اُبھرنے لگا، تو خود ان کے انگریز مربیوں ہی نے اس جذبہ کے خروج کا راستہ پیدا کیا۔ پہلا شخص جس کے دماغ میں ’’انڈین نیشنل کانگریس‘‘ قائم کرنے کا خیال آیاوہ ایک انگریز مسٹر ہیوم (Hume)تھا۔ ابتداً اس کے پیشِ نظر محض ایک ایسی انجمن بنانے کا تصوّر تھا جس میں ہندستان کے سیاسی دماغ مجتمع ہو کر تبادلہ خیالات کیا کریں‘ اور اس طرح حکمرانوں کو اپنے محکموں کے داعیات سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہے۔اس غرض کے لیے اس کی تجویز تھی‘ کہ جس صوبہ میں اس انجمن کا اجتماع ہو وہیں کا گورنر اس کی صدارت کرے مگر لارڈ ڈفرن نے، جو اس وقت ہندستان کا وائسرائے تھا، اس کے خیالات کو بدل کر ایک دوسری راہ پر ڈال دیا۔ اس نے یہ رائے دی کہ:
ہندستان میںایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کی حیثیت یہاں وہی ہو‘ جو انگلستان میں حزب الاختلاف (opposition) کی ہے تاکہ وہ حکومت پر نکتہ چینی کرکے اس کے نقائص کو دور کرتی رہے۔ نیز اس جماعت کو مستقل بالذات ہونا چاہیے۔ گورنر کی صدارت اس کی آزادی رائے میں خلل انداز ہو گی۔
انگلستان میںلارڈرپن، لارڈ ڈلہوزی، سر جیمز کیرڈ (caird)، جان برائٹ، مسٹر ریڈ، مسٹر سلیگ (Slagg) اور دوسرے سیاسی مبصرین نے بھی لارڈ ڈفرن کی اس رائے کو پسند کیا اور اس طرح ۱۸۸۵ء میں کانگریس کی تاسیس{ FR 2940 } ہوئی۔
سیاسی عمل کی یہ ابتدا جس طرح انگریزی افکار اور انگریزی تدبر کی رہنمائی میںہوئی، اسی طرح مقاصد اور ان کے حصول کی صورت کا تعین بھی آپ سے آپ انگریزی اثرات کے تحت اور انگریزی دستور حکومت کے نمونے پر ہوتا رہا۔ کانگریس کو اوّل یوم پیدائش ہی میں ’’انڈین نیشنل کانگریس‘‘ کے نام سے موسوم کیا گیا، گویا کہ ’’انڈین نیشن‘‘ کے نام سے کوئی قوم موجود تھی‘ اور یہ اس کی ایک اجتماعی ہیئت (کانگریس) بنائی جا رہی تھی۔ انگریزی تعلیم کے جو اثرات ان لوگوں کے دماغ پر پڑے تھے، ان کا اثر اتنا گہرا تھا‘ کہ انہوں نے ایک ملک کی آبادی کا ایک قوم ہونا، بطور ایک بدیہی کلیہ کے تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے لیے وہ واقعات کی شہادت کو بھی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ کانگریس کے پہلے اجلاس میںجو مقاصد اس جمعیت کے لیے تجویز ہوئے تھے ان میں سے دوسرا مقصد یہ تھا:
قومی وحدت کے ان داعیات کا نشوو ارتقا اور استحکام جو ہمارے محبوب لارڈرپن کے ہمیشہ یادگار رہنے والے عہد حکومت میںپیدا ہوئے ہیں۔{ FR 2941 }
دوسرے اجلاس کے خطبہ صدارت میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں :
ایک قومی کانگریس کو ان امور تک اپنے تئیں محدود رکھنا چاہیے جن میں پوری قوم براہِ راست حصہ دار ہو‘ اور اصلاح معاشرت اور دوسرے طبقہ وار مسائل کو طبقات کی کانگریسوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔{ FR 2942 }
یہ وطنی قومیّت اور واحد قومیّت کا تخیل اس تحریک کے مایہ خمیر کا پہلا عنصر ہے۔ جس طرح ۱۸۸۵ء میں بینر جی اور نورو جی ’’ہندوستانی قوم‘‘ کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح آج گاندھی جی اور نہرو جی بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ محض ذکر کرتے تھے‘ اور یہ اس کو زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔گاندھی جی استفہام انکاری کے لہجہ میں پوچھتے ہیں‘ کہ
ہندستان ایک ملک اور ایک قوم ہے‘ یا بہت سے ملک اور بہت سی قومیں؟ { FR 2943 }
اور خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں‘ کہ جو لوگ اس کو ایک ملک اور ایک قوم سمجھتے ہیںانہیں اس پر اعتراض نہ ہونا چاہیے‘ کہ اگر مدراس کا وزیر اعظم ایک قوم کے لیے ایک زبان بنانے میںکرنمیل لاامنڈمنٹ ایکٹ کی جابرانہ طاقت استعمال کرے۔ نہرو جی استفہام کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے اور قطعی طور پر اعلان کرتے ہیں‘ کہ ہندستان میں صرف ایک قوم بستی ہے‘ جس کا نام ہندستانی ہے۔ جدا جدا مستقل قوموں کا یہاں وجود ہی نہیںہے۔
دوسرا بنیادی تصوّر جو انگریزی تعلیم اور انگریزی مربیوں کی سیاسی تربیت سے اخذ کیا گیا وہ قومی جمہوریت (national democracy) کا تصوّر تھا۔ جمہوری ادارت کی مختلف صورتیں جو دنیا میں رائج ہیں‘ اور رائج رہی ہیں، ان میں ایک نہایت ناقص اور قدامت پرستانہ صورت وہ ہے‘ جو انگلستان میں قائم ہے۔ لیکن ہمارا ہندستانی وطن پرست چونکہ انگریز کا شاگرد ہے، اسی سے جمہوریت کا نام اس نے سنا ہے،اور اسی کے جمہوری نظام کا نقشہ اس نے دیکھا ہے،اس لیے یہ جب ’’جمہوریت‘‘ کا لفظ بولتا ہے‘ تو اس کے سامنے جمہوری دستور کے وہی اصول اور وہی طریقے ہوتے ہیں‘ جو انگلستان میں رائج ہیں۔ نمائندگی، انتخاب، ذمّہ دار حکومت اور دستور سلطنت کی ساری تفصیلات کو یہ جوں کا توں انگلستان سے ہندستان اُٹھا لانا چاہتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ قوموں اور ملکوںکے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جس قسم کے ادارات ایک ملک کے مناسب حال ہوں، لازم نہیں کہ وہ دوسرے ملک کے قامت پر بھی راست آسکیں۔ قوّتِ تمیز اور اجتہادِ فکر کے بغیر محض دوسروں کی نقّالی کرنا اصولاً بھی غلط ہے‘ اور عملاً بھی مشکل، بلکہ مضرت رساں، مگر مختلف اسباب ایسے پیدا ہو گئے ہیں‘ جو اس حقیقت کے بار بار سامنے لائے جانے پر بھی ہمارے وطن پرستوں کو اس کے ادراک سے روکتے ہیں۔ ایک گروہ غلامانہ ذہنیت اور محدود واقفیت کی بنا پر یہ سمجھتا ہے‘ کہ ’’جمہوری ادارت‘‘کا اطلاق صرف انگریزی طرز کے ادارات پر ہی ہوتا ہے‘ اور ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرز کی مخالفت کرنا نفس جمہوری ادارت کی مخالفت کرنا ہے۔د وسرا گروہ انگریزی نمونہ کی جمہوریت کو غلط سمجھتا ہے، مگر اس پر شکست خوردہ ذہنیت کا غلبہ ہے‘ اور وہ سمجھتا ہے‘ کہ جمہوری نظام، جو ہمارے برطانوی آقا اپنے ملک سے لائے ہیں‘ اور جس کی پشت پر مشین گن کی طاقت ہے، ہندستان میں رائج ہونا ہے‘ اور ہو کر رہے گا۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے‘ کہ اس کے آگے سپر رکھ دو۔ تیسرا گروہ جو کانگریس کا اصلی کار فرما اور کارکن گروہ ہے، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ خود غرضانہ ذہنیت سے بھی ماؤف ہے۔انگریزی طرز جمہوریت کوقبول کرنے میں سراسر اسی کا فائدہ ہے، کیونکہ یہ طرز جمہوریت اکثریت کو مالک الملک لاشریک لہا بنا دیتا ہے۔ اور اتفاق سے یہی گروہ یہاں اکثریت میں ہے۔ لہٰذا یہ کہتا ہے‘ کہ ہندستان میں واحد قومیّت کی بنیاد پر ایک ’’ڈیمو کریٹک اسٹیٹ‘‘ قائم ہونا چاہیے۔۱۸۸۵ء سے ۱۹۳۸ء تک ۵۳ سال کی مدت میں کانگریس کے مطالبات کی صورتیں بہت کچھ بدلی ہیں۔ پہلے سرکار سے مطالبہ کیا جاتا تھا‘ کہ ہمارے لیے ایک ایسا دستور حکومت بنا دو جس میں گورنمنٹ اہلِ ملک کے سامنے جوابدہ ہو۔ اب یہ مطالبہ ہے‘ کہ ہم خود اپنا دستور بنائیں گے۔ بظاہر پہلے موقف سے دوسرا موقف بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ مگر اصولی حیثیت سے ’’ڈیمو کریسی‘‘ کا جو تصوّر ۱۸۸۵ء میںتھا، بعینہ آج بھی وہی ہے۔ خواہ دستور حکومت سرکار بنائے یا یہ خود بنائیں۔
وطن پرستی کی اس تحریک میں انگریزی آقاؤں کا اثر محض علمی و نظری حیثیت سے ہی نہیں ہے‘ بلکہ تقریبا ۸۰ سال سے جو سیاسی تربیت ہندوستانیوںکو ان کے یہ آقا دے رہے ہیں۔ وہ عملاً بھی انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ ۱۸۶۱ء سے ۱۹۳۵ء تک جتنے دستوری تغیّرات اس ملک میں ہوئے ہیں‘ اور نظم و نسق حکومت میں ہندوستانیوں کو شریک کرنے کی جتنی صورتیں اختیار کی گئی ہیں، ان سب میں انگریز کی اس فطری کمزوری کا اثر نمایاں نظر آتا ہے‘ کہ وہ اپنے ملک کے جمہوری ادارات کو آئیڈیل سمجھتا ہے‘ اور اس میں اتنی اجتہادی صلاحیّت نہیںہے‘ کہ مختلف حالات کے لیے مختلف اصول وضع کر سکے۔ اگرچہ ابتداء سے اب تک ہر زمانہ میں انگریز مدبرین نے اس بات کواصولاً تسلیم کیا ہے‘ کہ ہندوستان انگلستان نہیں ہے‘ اور یہاں آنکھیں بند کرکے انگریزی طرز کے جمہوری ادارت قائم کرنا درست نہیں۔ مگر وہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی فطرت سے مجبور ہیںکہ ان کے ذہن میںہر طرف سے پھر کر جمہوریت کے وہی تصوّرات اور وہی رنگ ڈھنگ آجاتے ہیں‘ جن کے ماحول میں خود انہوں نے پرورش پائی ہے۔ وہ غیر شعوری طور پر اہلِ ہند کو ایک قوم فرض کر لیتے ہیں‘ جس طرح اہلِ انگلستان ایک قوم ہیں۔ وہ جائز سمجھتے ہیںکہ یہاں ڈیمو کریسی کے وہی اصول اختیار کیے جائیں جو واحد قومیّت ہی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ حالات کی رعایت زیادہ سے زیادہ ان کو جس چیز کے لیے آمادہ کر سکتی ہے۔ وہ بس جُدا گانہ انتخاب ہے، یعنی یہ کہ ہندستان کی مختلف قوموں کو جنہیں وہ ایک قوم کے مختلف فرقے سمجھتے ہیں۔ اپنے ہی منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعہ سے اپنی خواہشات کے اظہار کا موقع مل جائے۔ مگر کوئی شخص کسی دلیل سے بھی یہ بات ان کے ذہن میں نہیں بٹھاسکتا کہ جداگانہ انتخاب اس وقت بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے‘ جب ان مختلف قوموںکے مجموعہ کو ایک قرار دے کر اکثریت کی حکومت کا جمہوری قاعدہ نافذ کر دیا جائے۔ انہوں نے میونسپلٹیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں سے لے کر صوبوں اور مرکز کی قانون سازمجالس تک جتنے جمہوری ادارے اس ملک میں قائم کیے، ان سب میں کثرت رائے کے غلبہ کا اصول یکساں طور پر رائج کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ ہندستان میں جو قوم کْثیر التعداد واقع ہوئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت کی مالک ہوتی چلی گئی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا بدترین نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ کثیر التعداد قوم اس سیاسی غلبہ کو اپنا فطری اور اخلاقی حق سمجھنے لگی اور قلیل التعداد قومیں اس فریب میں مبتلا ہو گئیں کہ جمہوریت کا مفہوم غلبہ اکثریت کے سوا اور کچھ نہیں، ان کو خود بھی اپنی مغلوبیت پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ انگلستان سے جو چیز آئے اس کے عین حق ہونے میں تو کلام ہی نہیں ہو سکتا۔
جس ملک میں ذہنی غلامی اس حد تک پہنچ چکی ہو‘ کہ کسی چیز کے بجا و درست ہونے کے لیے محض صاحب بہادر کے قول و فعل کی سند کافی سمجھی جائے، حتیٰ کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر صاحب بہادر چائے میں برف ڈال کر پیتے ہوئے دیکھے جائیں تو غلام ہندستانی گھر پہنچ کر برف زدہ چائے پینے لگے، وہاں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ صاحب نے جمہوریت کا جو مفہوم بتایا ہے اس کے درست ہونے میں شک کیا جائے گا۔ یہاں آزادی کے مدعی ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہیں، مگر دماغوں کی غلامی ان سب کا مشترک سرمایہ ہے۔ جو لوگ یہاں آزاد خیالوں کے سر تاج سمجھے جاتے ہیں، ان کی غلام فطرتی بھی یہاںتک بڑھی ہوئی ہے‘ کہ جب تک ایک وزیر ہند (لارڈ آلیویر) نے جُدا گانہ انتخاب کو جمہوریت و قومیّت کے منافی نہ قرار دیا تھا اس وقت تک یہ غریب اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھے‘ کہ واقعی یہ چیز اس درجہ منافی قومیّت و جمہوریت ہے، اور جب یہ بات صاحب کی زبان سے سن لی گئی‘ تو ڈاکٹر مونجے سے لے کر پنڈت جواہر لال نہرو تک ہر ایک اس زعم کے ساتھ اس کا اعلان کرنے لگا کہ جس قول کو سرکار والاتبار کی سند حاصل ہے اس کے برحق ہونے میں کس کو کلام کی جرأت ہو سکتی ہے۔ پھر جو صاحب یہاں آزاد خیالوں کے امام ہیں ان کا حال بھی یہ ہے‘ کہ سرکار کے قائم کیے ہوئے جمہوری ادارات کو جمہوریت کی ایک ہی فطری و بر حق صورت سمجھتے ہیں، اور ان ادارات کے اصول سے اختلاف کرنا ان کے نزدیک سیاسی اصلاح و ترقی کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ سیاسی اصلاح و ترقی کی صراط مستقیم ایک ہی ہے‘ جس کی طرف غلاموں کے ہادی برحق صاحب بہادر نے ان کی رہنمائی کی ہے، اور وہ بس یہ ہے‘ کہ مختلف قوموں کو ایک مجموعہ قرار دے کر اس میں غلبہ اکثریت کا جمہوری اصول نافذ کر دیا جائے۔ صاحب کے دئیے ہوئے اس علم پر غلام دماغوں کا یقین واذعان اور انشراح و اطمینان اتنا بڑھا ہوا ہے‘ کہ وہ ریاضی کے اصول موضوعہ کی طرح اسے بیان کرتے ہیں‘اور اپنی ذہنی غلامی کے راز کو چھپانے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے کہ انہیں اپنی ذہنی غلامی کا احساس تک نہیں رہا۔
قومیّت اور جمہوریت کے ساتھ ایک تیسرا اساسی تخیل بھی ہے‘ جو انہوں نے صاحب کی تعلیم و تربیت سے حاصل کیا ہے‘ اور وہ یہ کہ اسٹیٹ کو دنیوی (secular) یعنی غیر دینی ہونا چاہیے۔
غیر دینی کا ایک سادہ مفہوم یہ ہے‘ کہ اسٹیٹ کا اپنا کوئی مذہب نہ ہو۔ وہ بجائے خود دنیوی ہو۔ اس کی اساس کسی مخصوص شریعت پر نہ ہو۔ وہ کسی خاص مذہب کی نصرت و حمایت نہ کرے مگر اس کے ساتھ ہی وہ مخالف دین (anti religious) بھی نہ ہو بلکہ اپنے دائرے میں مذہبی نظامات کو تسلیم کرے اور ان کو حکومت کے اختیارات میں سے کم از کم اتنے اختیارات تفویض کر دے جو اندرونی تنظیم کے لیے ضروری ہیں۔ مثلا اپنے پیروؤں پر ٹیکس عائد کرنا، مذہبی قوانین کو ان پر نافذ کرنا اور ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا، عام اس سے کہ وہ علیحدہ مدارس کی شکل میں ہو یا مشترک تعلیمی نظام کے ماتحت ہو۔ نازی دور سے پہلے تک جرمنی میں غیر دینی اسٹیٹ کا یہی مفہوم تھا‘ اور اب بھی یوگوسلیویا، پولینڈ، لتھوانیا، فن لینڈ، اور ایستھونیا میں یہی مفہوم ہے۔ غیر دینی اسٹیٹ کا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے‘ کہ وہ دین کی نفی (negation) پر قائم ہو، مخالف ِدین ہو، اس میں کسی دینی نظام کو تسلیم نہ کیا جائے۔ باشندوں کی اس حیثیت کو کہ وہ کسی خاص دین کے پیرو ہیں بالکل نظر انداز کر دیا جائے‘ اور عمومی حاکمیّت (popular sovereignty) کی تعبیر یہ کی جائے‘ کہ باشندگانِ ملک ہونے کی حیثیت سے تو سب باشندے حاکمیّت میں حصہ دار ہیں، مگر ایک مذہب کے پیرو ہونے کی حیثیت سے اس حاکمیّت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لہٰذا وہ خود اپنی حکومت سے بھی اپنے دینی نظام کی ترقی و استحکام کے لیے کوئی طاقت حاصل نہیں کر سکتے۔ لادینی کے اس مفہوم نے یورپ میں دو مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ ایک ظالمانہ (aggressive) جس میں حکومت کا ارادہ یہ ہوتا ہے‘ کہ مذہبی لوگوں کو لامذہب بنایا جائے۔ اس کی مثال روس ہے۔ دوسری صورت معتدل ہے‘ جس میں حکومت کی پالیسی یہ ہوتی ہے‘ کہ مذہبی نظامات کو زندگی کی طاقت پیدا کرنے والے تمام وسائل سے محروم کر دیا جائے‘ تاکہ وہ خود سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اس کی مثال چیکو سلواکیا ہے، جہاں تعلیم کا نظام کلیۃً حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے دینی عنصر کو قطعاً خارج کر دیا گیا ہے، اور حکومت سرکاری طور پر کسی قوم کے دینی نظام کو تسلیم نہیں کرتی۔
ہندستان میںہمارے آقاؤں نے جو طریق کار اختیار کیا ہے وہ ایک عجیب قسم کی معجون مرکب ہے۔بادشاہ سلامت حامی دین (defender of the faith) بھی ہیں‘ اور اسٹیٹ کی طرف سے ایک مذہبی محکمہ (ecclesiastical department) بھی قائم ہے۔اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے‘ کہ سلطنت کا کوئی مذہب نہیں ہے‘ اور اس کا مذہب نہ ہونے کے معنی یہ ہیں‘ کہ وہ مذہبی رواداری کے اصول پر قائم ہے۔ (یعنی لادینی کا پہلا مفہوم) مگر عملاً باشندگانِ ملک کے مذہب سے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے‘ جو چیکو سلواکیا کی روش سے ملتا جلتا ہے۔ اس عجیب مکسچر کی تحلیل اگر سائنٹفک طریقہ سے کی جائے‘ تو اس کے تین اجزاء برآمد ہوں گے۔
۱- مذہبی رواداری کا اعلان و اظہار
۲- ایک خاص عقیدہ و مسلک کی طرف نظرِ عنایت
۳- دوسرے تمام عقائد و مسلک کے ساتھ سنگدلانہ سرد مہری
ہندوستان میں’’دنیوی‘‘ اسٹیٹ کا یہ مرکب تصوّر فکر و عمل دونوں حیثیتوں میںڈیڑھ سو برس سے پرورش پا رہا ہے‘ اور ہمارے وطن پرستوں نے بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی تصوّر کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ ان کا ادعا یہ ہے‘ کہ ہماری تحریک غیر دینی ہے‘ اورہم ایسا دنیوی اسٹیٹ چاہتے ہیں‘ جس کی بنا کسی مذہب پر نہ ہو گی، مگر اس میں مذہبی رواداری ہو گی۔ یہ آقایان نامدار کے بنائے ہوئے مکسچر کا پہلا جزو ہے۔ا ور دوسرا جزو یہ ہے‘ کہ ان کا لیڈر({ FR 2944 })ایک ’’مہاتما‘‘ ہے، جو صداقت (truth) اور اہمسا (non-violence) کے خالص ہندوانہ تصوّرات کا علم بردار اور مبلغ بن کر اُٹھا ہے۔ جس کے تصورات، جنگ ِ آزادی کی فکری بنیاد ہیںجو صاف کہتا ہے‘ کہ عدم تشدد پالیسی نہیں‘ بلکہ دین و ایمان ہے۔ اس کی رہنمائی میں تمام باشندگانِ ہند کے لیے سرکاری طور پر عمومی تعلیم کے خاکے بنائے جاتے ہیں‘ اور ان سب میں اس کے دین و ایمان کو ا ساسی حیثیت دی جاتی ہے۔{ FR 2945 } اب رہ گیا تیسرا جزو تو اس کی بھی پوری مقدار اس معجون میں شریک کی گئی ہے۔ صاف صاف کہا جا چکا ہے‘ کہ باشندوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام کرنا اسٹیٹ کے فرائض سے خارج ہے، اور اس کے برعکس یہ چیز اسٹیٹ کے فرائض میں داخل ہے‘ کہ باشندوں کو جبراً ایسی تعلیم دے جو ان کے ذہن سے اپنے مذہب کی برتری کا خیال نکال دے۔ خود مہاتما گاندھی جنہوں نے اپنے مذہب کو بہ اصرار واردھا اسکیم کا جزو لاینفک بنوایا ہے، اپنے مذہب کے سوا دوسرے تمام مذاہب کو نظامِ تعلیم سے خارج کر دینے کے لیے یہ دلیل ارشاد فرماتے ہیں :
تمام مذاہب کا یکساں لحاظ رکھنے کی تعلیم دینا ایک ایسی ضرورت ہے‘ جس کے حق میں میرے خیالات بہت سخت ہیں۔ جب تک ہم اس خوش گوار حالت (یعنی سب مذاہب کو ایک نظر سے دیکھنے اور سب کو مساوی طور پر برحق سمجھنے کی حالت) کو نہ پہنچ جائیں گے، اس وقت تک مختلف فرقوں میں حقیقی وحدت پیدا ہونے کی مجھے کوئی توقع نظر نہیں آتی۔میرے نزدیک یہ بات مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بچوں کے درمیان دوستانہ اسپرٹ کے نشوونما کو غارت کرنے و الی ہو گی اگر ان کو یہ سکھایا جائے‘ کہ ان کا مذہب دوسرے مذاہب سے بہتر ہے‘ یا یہ کہ وہی ایک سچا مذہب ہے۔ اگر قوم (؟ ہندستانی قوم) پر یہی اختصاصی جذبہ مستولی رہے ‘تو اس سے لازم آئے گا کہ یا تو ہر مذہب والوں کے الگ الگ مدرسے ہوںجن میں ہر ایک کو دوسرے پر طعن کرنے کی آزادی حاصل رہے، یا پھر مذہب کا نام لینے ہی کو کلیۃً ممنوع قرار دے دیا جائے۔ا س قسم کا طرزِعمل اختیار کرنے کے نتائج اتنے خوفناک ہیںکہ ان کا تصوّر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاق کے بنیادی اصول تمام مذاہب میں مشترک ہیں۔ وہ ضرور بچوں کوسکھائے جانے چاہئیں اور جہاں تک واردھا اسکیم کے تحت مدارس کا تعلق ہے۔ان میں بس اتنی ہی مذہبی تعلیم کو کافی سمجھنا چاہیے۔{ FR 2946 }
اسی خیال کی ترجمانی ایک دوسرے ذمّہ دار شخص مسٹر سمپور نانند (یو پی کے وزیر تعلیم) نے اپنی ایک تقریر میںکی ہے‘ جو انہوں نے ۴ اپریل ۱۹۳۸ء کو یو پی، کی لیجسلیٹو اسمبلی میں ارشاد فرمائی تھی :
ہر وہ شخص جو ہندو یا مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اس کو مدارس میں جاری کرنے پر زور دیتا ہے، وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ ہندستان میں یہ چیز مفقود ہونی چاہیے۔ ہم ایک ہندستانی تہذیب چاہتے ہیںجو ہندوؤں اور مسلمانوں اور دوسروں کے لیے جو اس ملک میں آئے ہیں‘ اور جنہوں نے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہے بالکل ایک ہے۔اگر کوئی شخص واقعی ملک کی ترقی میں کوشاں رہے ‘تو اس کو ایسی بات پر زور دینا چاہیے جس سے ہم میں تفرقے پیدا نہ ہوں‘ جو سب کے لیے ضرر رساں ہیں۔ بلکہ ایسے امور ہوں جن سے ہندستانی تہذیب کی تعمیر و ترکیب ہوتی ہو۔ تمام وہ باتیں جن سے ہم میں تفرقہ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے یقینا ملک کے ساتھ دشمنی کرتی ہیں۔ اس لیے ملک کا عام مفاد مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اُمید ہے‘ کہ وہ لوگ جو لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس میںہندو اور مسلم تہذیب قائم رکھنا چاہتے ہیں اس بات پر زور نہ دیں گے۔{ FR 2947 }
اسی تقریر کا ایک فقرہ یہ بھی ہے :
جب ہندو مسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب زندہ { FR 2949 }رہ سکے گی۔
ان تحریروں اور تقریروں سے صاف طور پرواضح ہوتا ہے‘ کہ ہندستانی وطن پرست جو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ایک معنی میں دینی اسٹیٹ ہے اگر دین سے مراد مہاتما گاندھی کا دین لیا جائے،ا ور ایک معنی میں لادینی بلکہ مخالف دین (anti religious) اسٹیٹ ہے اگر دین سے مراد ہندستان کے ان باشندوں کا دین لیا جائے‘ جو دینِ گاندھی کے پیرو نہیں ہیں۔ان کے حق میں اس اسٹیٹ کا روّیہ غیر جانب دارانہ رواداری کا نہ ہو گابلکہ چیکو سلواکیہ کی طرح غیر ہم دردانہ اور ایک حد تک مخالفانہ ہو گا۔ اس کا مطمح نظر صریحاً یہ بتایا جا رہا ہے‘ کہ مختلف قوموں کی تہذیبیں کسی نہ کسی طرح فنا ہو جائیں، ان کا مذہبی زاویۂ نظر بدل جائے، اور وہ تمام مذاہب کو برابر سمجھنے لگیں، یعنی کسی مذہب کے پیرو نہ رہیں، کیونکہ ایک مذہب کی پیروی کے لیے اس کو سب سے بہتر اور صحیح تر جاننا فطری طور پر ناگزیر ہے۔ا س کے بعد یہ خیال کرنے کاکوئی موقع ہی نہیں رہتا کہ ایسا اسٹیٹ کسی مذہبی نظام کو قانوناً تسلیم کرے گا اور اس کو تعلیم اور اندرونی تنظیم کے لیے وہ حقوق اور اختیارات دے گا‘ جن کی مثالیں ہم نے اوپر یورپ کے متعدّد ممالک سے پیش کی ہیں۔
ان تشریحات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے‘ کہ ہمارے وطن پرست ہندستان کے لیے جس قسم کی آزاد حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیادی خصوصیات تین ہیں:
۱- ’’نیشنل اسٹیٹ‘‘ اس معنی میںکہ باشندگانِ ہندستان کی پوری آبادی کو ایک قوم قرار دیا جائے‘ اور جُدا گانہ قومیّتوں کی نفی کر دی جائے۔
۲- ’’جمہوری اسٹیٹ‘‘ اس معنی میںکہ باشندگانِ ہند کو ایک مجموعہ قرار دے کر اس میں غلبہ اکثریت کا اصول نافذ کیا جائے۔
۳- ’’دنیوی اسٹیٹ‘‘ اس معنی میں کہ جہاں تک ہندستان کی مختلف قوموں کے مذہب کا تعلق ہے۔ ان کے لحاظ سے وہ ایک لادینی اسٹیٹ ہو۔{ FR 2950 }
اب ہم کو دیکھنا چاہیے‘ کہ اس نوعیت کا اسٹیٹ دراصل کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو اپنا مطمح نظر بنا سکتے ہیں؟ کیا ایسے اسٹیٹ میں ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت برقرار بھی رہ سکتی ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے‘ کہ ہم اس کو قائم کرنے کی جدوجہد میں حصہ لیں، یا صبر و سکون کے ساتھ اس کے قیام کو گوارا کریں؟ آئندہ باب میں ہم ان سوالات پر بحث کریں گے۔
خ خ خ
![Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1] Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w[1]](https://mawdudicentury.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/Maududi-wide-pyram9y7glcr3vj7bekxkoxojmxriq09jv4pmyp88w1-q09onzg276g85rarxgw4bcyyzm4zai9gnizfi4wohs.png)
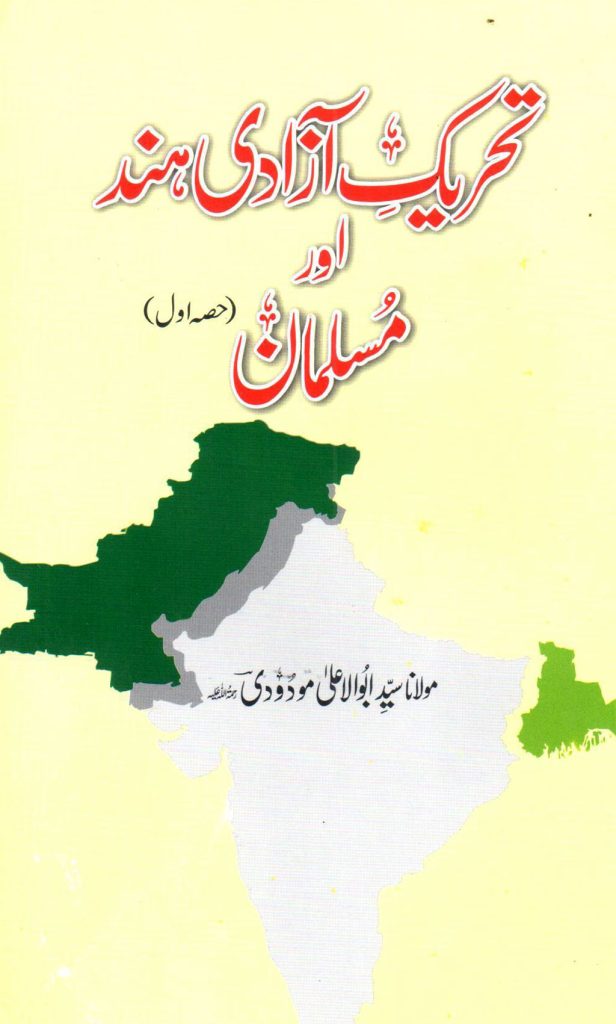

 by
by